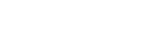سوراج کے لیے
مجھے سن یاد نہیں رہا، لیکن وہی دن تھےجب امرتسر میں ہر طرف ’’انقلاب زندہ باد‘‘ کے نعرے گونجتے تھے۔ ان نعروں میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک عجیب قسم کا جوش تھا۔۔۔ ایک جوانی۔۔۔ ایک عجیب قسم کی جوانی۔ بالکل امرتسر کی گجریوں کی سی، جو سر پر اپلوں کے ٹوکرے اٹھائے بازاروں کو جیسے کاٹتی ہوئی چلتی ہیں۔۔۔ خوب دن تھے۔ فضا میں جو وہ جلیانوالہ باغ کے خونیں حادثے کا اداس خوف سمویا رہتا تھا، اس وقت بالکل مفقود تھا۔ اب اس کی جگہ ایک بے خوف تڑپ نے لے لی تھی۔۔۔ ایک اندھا دھند جَست نے جو اپنی منزل سے ناواقف تھی۔
لوگ نعرے لگاتے تھے، جلوس نکالتے تھے اور سیکڑوں کی تعداد میں دھڑادھڑ قید ہو رہے تھے۔ گرفتار ہونا ایک دلچسپ شغل بن گیا تھا۔ صبح قید ہوئے۔ شام چھوڑ دیے گئے، مقدمہ چلا، چند مہینوں کی قید ہوئی، واپس آئے، ایک نعرہ لگایا، پھر قید ہوگئے۔
زندگی سے بھرپور دن تھے۔ ایک ننھا سا بلبلہ پھٹنے پر بھی ایک بہت بڑا بھنور بن جاتا تھا۔ کسی نے چوک میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، ’’ہڑتال ہونی چاہیے۔‘‘ چلیے جی، ہڑتال ہوگئی۔ ایک لہر اٹھی کہ ہر شخص کو کھادی پہننی چاہیے تاکہ لنکا شائز کے سارے کارخانے بند ہو جائیں۔۔۔ بدیشی کپڑوں کا بائیکاٹ شروع ہو گیا اور ہر چوک میں الاؤ جلنے لگے، لوگ جوش میں آکر کھڑے کھڑے وہیں کپڑے اتارتے اور الاؤ میں پھینکتے جاتے، کوئی عورت اپنے مکان کے شہ نشین سے اپنی ناپسندیدہ ساڑی اچھالتی تو ہجوم تالیاں پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ لال کرلیتا۔
مجھے یاد ہے ،کوتوالی کے سامنے ٹاؤن ہال کے پاس ایک الاؤ جل رہا تھا۔۔۔ شیخو نے، جو میرا ہم جماعت تھا، جوش میں آکر اپنا ریشمی کوٹ اتارا اور بدیشی کپڑوں کی چتا میں ڈال دیا۔ تالیوں کا سمندر بہنے لگا۔ کیونکہ شیخو ایک بہت بڑے ’’ٹوڈی بچے‘‘ کا لڑکا تھا، اس غریب کا جوش اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اپنی بوسکی کی قمیص اتار وہ بھی شعلوں کی نذر کردی، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اس کے ساتھ سونے کے بٹن تھے۔
میں شیخو کا مذاق نہیں اڑاتا، میرا حال بھی ان دنوں بہت دگرگوں تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں سے پستول ہاتھ میں آجائے تو ایک دہشت پسند پارٹی بنائی جائے۔ باپ گورنمنٹ کا پنشن خوار تھا، اس کا مجھے کبھی خیال نہ آیا۔ بس دل و دماغ میں ایک عجیب قسم کی کھد بد رہتی تھی۔ بالکل ویسی ہی جیسی فلاش کھیلنے کے دوران دوپان میں رہا کرتی ہے۔
اسکول سے تو مجھے ویسے ہی دلچسپی نہیں تھی مگر ان دنوں تو خاص طور پر مجھے پڑھائی سے نفرت ہوگئی تھی۔۔۔ گھر سے کتابیں لے کر نکلتا اور جلیانوالہ باغ چلا جاتا، اسکول کا وقت ختم ہونے تک وہاں کی سرگرمیاں دیکھتا رہتا یا کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر دورمکانوں کی کھڑکیوں میں عورتوں کو دیکھتااور سوچتا کہ ضرور ان میں سے کسی کو مجھ سے عشق ہو جائے گا۔۔۔ یہ خیال دماغ میں کیوں آتا، اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔
جلیانوالہ باغ میں خوب رونق تھی۔ چاروں طرف تنبو اور قناتیں پھیلی ہوئی تھیں، جو خیمہ سب سے بڑا تھا، اس میں ہر دوسرے تیسرے روز ایک ڈکٹیٹر بناکے بٹھا دیا جاتا تھا۔ جس کو تمام والنٹیر سلامی دیتے تھے۔ دو تین روز یا زیادہ سے زیادہ دس پندرہ روز تک یہ ڈکٹیٹر کھادی پوش عورتوں اور مردوں کی نمسکاریں، ایک مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ وصول کرتا۔ شہر کے بنیوں سے لنگر خانے کے لیے آٹا چاول اکٹھا کرتا اور دہی کی لسی پی پی کر، جو خدا معلوم جلیانوالہ باغ میں کیوں اس قدر عام تھی، ایک دن اچانک گرفتار ہو جاتا اور کسی قید خانے میں چلا جاتا۔
میرا ایک پرانا ہم جماعت تھا شہزادہ غلام علی، اس سے میری دوستی کا اندازہ آپ کو ان باتوں سے ہوسکتا ہے کہ ہم اکٹھے دو دفعہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہو چکے تھے اور ایک دفعہ ہم دونوں گھر سے بھاگ کربمبئی گئے ،خیال تھا کہ روس جائیں گے مگر پیسے ختم ہونے پر جب فٹ پاتھوں پرسونا پڑا تو گھر خط لکھے، معافیاں مانگیں اور واپس چلے آئے۔شہزادہ غلام علی خوبصورت جوان تھا۔ لمبا قد، گورا رنگ جو کشمیریوں کا ہوتا ہے۔ تیکھی ناک، کھلنڈری آنکھیں، چال ڈھال میں ایک خاص شان تھی جس میں پیشہ ور غنڈوں کی کج کلاہی کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔
جب وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا تو شہزادہ نہیں تھا۔ لیکن جب شہرمیں انقلابی سرگرمیوں نے زور پکڑا اور اس نے دس پندرہ جلسوں اور جلوسوں میں حصہ لیا تو نعروں ،گیندے کے ہاروں، جوشیلے گیتوں اور لیڈی والنٹیرز سے آزادانہ گفتگوؤں نے اسے ایک نیم رس انقلابی بنا دیا، ایک روز اس نے پہلی تقریر کی، دوسرے روز میں نے اخبار دیکھے تو معلوم ہوا کہ غلام علی شہزادہ بن گیا ہے۔
شہزادہ بنتے ہی غلام علی سارے امرتسر میں مشہور ہوگیا۔ چھوٹا سا شہر ہے، وہاں نیک نام ہوتے یا بدنام ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یوں تو امرتسری عام آدمیوں کے معاملے میں بہت حرف گیر ہیں، یعنی ہر شخص دوسروں کے عیب ٹٹولنے اور کرداروں میں سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہےلیکن سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے معاملے میں امرتسری بہت چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ ان کو دراصل ہر وقت ایک تقریر یا تحریک کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ انھیں نیلی پوش بنا دیجیے یا سیاہ پوش، ایک ہی لیڈر چولے بدل بدل کر امرتسر میں کافی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ تمام بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں تھے اور ان کی گدیاں خالی تھیں۔ اس وقت لوگوں کو لیڈروں کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہ تھی۔ لیکن وہ تحریک جو کہ شروع ہوئی تھی اس کو البتہ ایسے آدمیوں کی اشد ضرورت تھی جو ایک دو روز کھادی پہن کر جلیانوالہ باغ کے بڑے تنبو میں بیٹھیں، ایک تقریر کریں اور گرفتار ہو جائیں۔
ان دنوں یورپ میں نئی نئی ڈکٹیٹر شپ شروع ہوئی تھی، ہٹلر اور مسولینی کا بہت اشتہار ہورہا تھا۔ غالباً اس اثر کے ماتحت کانگریس پارٹی نے ڈکٹیٹر بنانے شروع کردیے تھے۔ جب شہزادہ غلام علی کی باری آئی تو اس سے پہلے چالیس ڈکٹیٹر گرفتار ہو چکے تھے۔
جونہی مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح غلام علی ڈکٹیٹر بن گیا ہے تو میں فوراً جلیانوالہ باغ میں پہنچا۔ بڑے خیمے کے باہر والنٹیروں کا پہرہ تھا۔ مگر غلام علی نے جب مجھے اندر سے دیکھا تو بلا لیا۔۔۔ زمین پر ایک گدیلا تھا جس پر کھادی کی چاندنی بچھی تھی۔ اس پر گاؤ تکیوں کا سہارا لیے شہزادہ غلام علی چند کھادی پوش بنیوں سے گفتگو کررہا تھا جو غالباً ترکاریوں کے متعلق تھی۔ چند منٹوں ہی میں اس نے یہ بات چیت ختم کی اور چند رضا کاروں کو احکام دے کروہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کی یہ غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر میرے گدگدی سی ہو رہی تھی۔ جب رضا کار چلے گئے تو میں ہنس پڑا۔
’’سنا بے شہزادے۔‘‘
میں دیر تک اس سے مذاق کرتا رہا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ غلام علی میں تبدیلی پیدا ہوگئی ہے۔ ایسی تبدیلی جس سے وہ باخبر ہے ۔ چنانچہ اس نے کئی بار مجھ سے یہی کہا، ’’نہیں سعادت۔۔۔ مذاق نہ اڑاؤ۔ میں جانتا ہوں میرا سر چھوٹا اور یہ عزت جو مجھے ملی ہے بڑی ہے۔۔۔ لیکن میں یہ کھلی ٹوپی ہی پہنے رہنا چاہتا ہوں۔‘‘
کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے دہی کی لسی کا ایک بہت بڑا گلاس پلایا اور میں اس سے یہ وعدہ کرکے گھر چلاگیا کہ شام کو اس کی تقریر سننے کے لیے ضرور آؤں گا۔شام کو جلیانوالہ باغ کھچا کھچ بھرا تھا۔ میں چونکہ جلدی آیا تھا، اس لیے مجھے پلیٹ فارم کے پاس ہی جگہ مل گئی۔۔۔ غلام علی تالیوں کے شور کے ساتھ نمودار ہوا۔۔۔ سفید بے داغ کھادی کے کپڑے پہنے وہ خوبصورت اور پر کشش دکھائی دے رہا تھا۔۔۔ وہ کج کلاہی کی جھلک جس کا میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں،اس کی اس کشش میں اضافہ کررہی تھی۔تقریباً ایک گھنٹے تک وہ بولتا رہا۔ اس دوران میں کئی بارمیرے رونگٹے کھڑے ہوئے اور ایک دو دفعہ تو میرے جسم میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بم کی طرح پھٹ جاؤں۔ اس وقت میں نے شاید یہی خیال کیا تھا کہ یوں پھٹ جانے سے ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔
خدا معلوم کتنے برس گزر چکے ہیں۔ بہتے ہوئے احساسات اور واقعات کی نوک پلک جو اس وقت تھی، اب پوری صحت سے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ کہانی لکھتے ہوئے میں جب غلام علی کی تقریر کا تصور کرتا ہوں تو مجھے صرف ایک جوانی بولتی دکھائی دیتی تھی، جو سیاست سے بالکل پاک تھی۔۔۔ اس میں ایک ایسے نوجوان کی پر خلوص بےباکی تھی جو ایک دم کسی راہ چلتی عورت کو پکڑلے اور کہے،’’دیکھو میں تمہیں چاہتا ہوں۔‘‘ اور دوسرے لمحے قانون کے پنجے میں گرفتار ہو جائے ۔اس تقریر کے بعد مجھے کئی تقریریں سننے کا اتفاق ہوا ہےمگر وہ خام دیوانگی، وہ سرپھری جوانی، وہ الھڑ جذبہ، وہ بے ریش و بروت للکار جو میں نے شہزادہ غلام علی کی آواز میں سنی، اب اس کی ہلکی سی گونج بھی مجھے کبھی سنائی نہیں دی۔ اب جو تقریریں سننے میں آتی ہیں،وہ ٹھنڈی سنجیدگی، بوڑھی سیاست اور شاعرانہ ہوش مندی میں لپٹی ہوتی ہیں۔
اس وقت دراصل دونوں پارٹیاں خام کار تھیں،حکومت بھی اور رعایا بھی۔ دونوں نتائج سے بے پروا، ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ حکومت قید کی اہمیت سمجھے بغیر لوگوں کو قید کررہی تھی اور جو قید ہوتے تھے ان کو بھی قید خانوں میں جانے سے پہلے قید کا مقصد معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دھاندلی تھی مگر اس دھاندلی میں ایک آتشیں انتشار تھا۔ لوگ شعلوں کی طرح بھڑکتے تھے، بجھتے تھے، پھر بھڑکتے تھے۔ چنانچہ اس بھڑکنے اور بجھنے، بجھنے اور بھڑکنے نے غلامی کی خوابیدہ، اداس اور جمائیوں بھری فضا میں گرم ارتعاش پیدا کردیا تھا۔
شہزادہ غلام علی نے تقریر ختم کی تو سارا جلیانوالہ باغ تالیوں اور نعروں کا دہکتا ہوا الاؤ بن گیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب میں اس سے الگ جا کر ملا اور مبارک باد دینے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا تو وہ کانپ رہا تھا۔ یہ گرم کپکپاہٹ اس کے چمکیلے چہرے سے بھی نمایاں تھی۔ وہ کسی قدر ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پرجوش جذبات کی دمک کے علاوہ مجھے ایک تھکی ہوئی تلاش نظر آئی، وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایک دم اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے علیحدہ کیا اور سامنے چنبیلی کی جھاڑی کی طرف بڑھا۔
وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کھادی کی بے داغ ساڑی میں ملبوس۔
دوسرے روز مجھے معلوم ہوا کہ شہزادہ غلام علی عشق میں گرفتار ہے۔ وہ اس لڑکی سے، جسے میں نے چنبیلی کی جھاڑی کے پاس باادب کھڑی دیکھا تھا،محبت کررہا تھا۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی کیونکہ نگار کو بھی اس سے والہانہ لگاؤ تھا۔ نگار جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک مسلمان لڑکی تھی۔۔۔ یتیم! زنانہ ہسپتال میں نرس تھی اور شاید پہلی مسلمان لڑکی تھی جس نے امرتسر میں بے پردہ ہوکر کانگریس کی تحریک میں حصہ لیا۔ کچھ کھادی کے لباس نے، کچھ کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے باعث اور کچھ ہسپتال کی فضا نے نگار کی اسلامی خوکو، اس تیکھی چیز کو جو مسلمان عورت کی فطرت میں نمایاں ہوتی ہے تھوڑا سا گھسا دیا تھا جس سے وہ ذرا ملائم ہوگئی تھی۔
وہ حسین نہیں تھی لیکن اپنی جگہ نسوانیت کا ایک نہایت ہی دیدہ چشم منفرد نمونہ تھی۔ انکسار، تعظیم اور پرستش کا وہ ملا جلا جذبہ جو آدرش ہندو عورت کا خاصہ ہے نگار میں اس کی خفیف سی آمیزش نے ایک روح پر ور رنگ پیدا کردیا تھا۔ اس وقت تو شاید یہ کبھی میرے ذہن میں نہ آتا، مگر یہ لکھتے وقت میں نگار کا تصور کرتا ہوں تو وہ مجھے نماز اور آرتی کا دلفریب مجموعہ دکھائی دیتی ہے۔شہزادہ غلام علی کی وہ پرستش کرتی تھی اور وہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھا ۔جب نگار کے بارے میں اس سے گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ کانگریس تحریک کے دوران میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں کے ملاپ سے وہ ایک دوسرے کے ہوگئے۔
غلام علی کا ارادہ تھا کہ قید ہونے سے پہلے پہلے وہ نگار کو اپنی بیوی بنالے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا کیونکہ قید سے واپس آنے پر بھی وہ اس سے شادی کرسکتا تھا۔ ان دنوں کوئی اتنی لمبی قید نہیں تھی۔ کم سے کم تین مہینے اور زیادہ سے زیادہ ایک برس۔ بعضوں کو تو پندرہ بیس روز کے بعد ہی رہا کردیا جاتا تھا تاکہ دوسرے قیدیوں کے لیے جگہ بن جائے۔ بہر حال وہ اس ارادے کو نگار پر بھی ظاہر کرچکا تھا اور وہ بالکل تیار تھی۔ اب صرف دونوں کو بابا جی کے پاس جا کر ان کا آشیرواد لینا تھا۔
بابا جی جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے بہت زبردست ہستی تھی۔ شہر سے باہر لکھ پتی صراف ہری رام کی شاندارکوٹھی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ یوں تو وہ اکثر اپنے آشرم میں رہتے جو انھوں نے پاس کے ایک گاؤں میں بنا رکھا تھا مگر جب کبھی امرتسر آتے تو ہری رام صراف ہی کی کوٹھی میں اترتے اور ان کے آتے ہی یہ کوٹھی بابا جی کے شیدائیوں کے لیے مقدس جگہ بن جاتی۔ سارا دن درشن کرنے والوں کا تانتا بندھا رہتا۔ دن ڈھلے وہ کوٹھی سے باہر کچھ فاصلے پر آم کے پیڑوں کے جھنڈ میں ایک چوبی تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو عام درشن دیتے، اپنے آشرم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے۔ آخر میں بھجن وغیرہ سن کر ہر روز شام کو یہ جلسہ ان کے حکم سے برخاست ہو جاتا۔بابا جی بہت پرہیز گار، خدا ترس، عالم اور ذہین آدمی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ اور اچھوت سب ان کے گرویدہ تھے اور انھیں اپنا امام مانتے تھے۔ سیاست سے گو باباجی کو بظاہر کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ پنجاب کی ہر سیاسی تحریک انہی کے اشارے پر شروع ہوئی اور انہی کے اشارے پر ختم ہوئی۔
گورنمنٹ کی نگاہوں میں وہ ایک عقدۂ لاینحل تھے، ایک سیاسی چیستاں ،جسے سرکارِ عالیہ کے بڑے بڑے مدبر بھی نہ حل کرسکتے تھے۔ بابا جی کے پتلے پتلے ہونٹوں کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ہزار معنی نکالے جاتے تھے مگر جب وہ خود اس مسکراہٹ کا بالکل ہی نیا مطلب واضح کرتے تو مرعوب عوام اور زیادہ مرعوب ہو جاتے۔
یہ جو امرتسر میں سول نافرمانی کی تحریک جاری تھی اور لوگ دھڑا دھڑ قید ہوررہے تھے، اس کے عقب میں جیسا کہ ظاہر ہے، بابا جی ہی کا اثر کارفرما تھا۔ ہر شام لوگوں کو عام درشن دیتے وقت وہ سارے پنجاب کی تحریک آزادی اور گورنمنٹ کی نت نئی سخت گیریوں کے متعلق اپنے پوپلے منہ سے ایک چھوٹا سا۔۔۔ ایک معصوم سا جملہ نکال دیا کرتے تھے، جسے فوراً ہی بڑے بڑے لیڈر اپنے گلے میں تعویذ بنا کرڈال لیتے تھے۔
لوگوں کا بیان ہے کہ ان کی آنکھوں میں ایک مقناطیسی قوت تھی، ان کی آواز میں ایک جادو تھا اور ان کا ٹھنڈا دماغ۔۔۔ ان کا وہ مسکراتا ہوتا دماغ، جس کو گندی سے گندی گالی اور زہریلی سے زہریلی طنز بھی ایک لحظے کے ہزارویں حصے کے لیے برہم نہیں کرسکتی تھی، حریفوں کے لیے بہت ہی الجھن کا باعث تھا۔
امرتسر میں بابا جی کے سیکڑوں جلوس نکل چکے تھے، مگر جانے کیا بات ہے کہ میں نے اور تمام لیڈروں کو دیکھا، ایک صرف ان ہی کو میں نے دور سے دیکھا نہ نزدیک سے۔ اسی لیے جب غلام علی نے مجھ سے ان کے درشن کرنے اور ان سے شادی کی اجازت لینے کے متعلق بات چیت کی تو میں نے اس سے کہا کہ جب وہ دونوں جائیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں۔
دوسرے ہی روز غلام علی نے تانگے کا انتظام کیا اور ہم صبح سویرے لالہ ہری رام صراف کی عالی شان کوٹھی میں پہنچ گئے۔ بابا جی غسل اور صبح کی دعا سے فارغ ہو کر ایک خوبصورت پنڈتانی سے قومی گیت سن رہے تھے۔ چینی کی بے داغ سفید ٹائلوں والے فرش پر آپ کھجور کے پتوں کی چٹائی پر بیٹھے تھے، گاؤ تکیہ ان کے پاس ہی پڑا تھا مگر انھوں نے اس کا سہارا نہیں لیا تھا۔کمرے میں سوائے ایک چٹائی کے، جس کے اوپر بابا جی بیٹھے تھے اور فرنیچر وغیرہ نہیں تھا۔ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سفید ٹائلیں چمک رہی تھیں۔ ان کی چمک نے قومی گیت گانے والی پنڈتانی کے ہلکے پیازی چہرے کو اور بھی زیادہ حسین بنا دیا تھا۔
بابا جی گو ستر بہتر برس کے بڈھے تھے مگر ان کا جسم (وہ صرف گیروے رنگ کا چھوٹا سا تہمد باندھے تھے) عمر کی جھریوں سے بے نیاز تھا، جلد میں ایک عجیب قسم کی ملاحت تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہر روز اشنان سے پہلے روغن زیتون اپنے جسم پر ملواتے ہیں۔شہزادہ غلام علی کی طرف دیکھ کروہ مسکرائے ،مجھے بھی ایک نظر دیکھا اور ہم تینوں کی بندگی کا جواب اسی مسکراہٹ کو ذرا طویل کرکے دیا اور اشارہ کیا کہ ہم بیٹھ جائیں۔
میں اب یہ تصویر اپنے سامنے لاتا ہوں تو شعور کی عینک سے یہ مجھے دلچسپ ہونے کے علاوہ بہت ہی فکر خیز دکھائی دیتی ہے۔ کھجور کی چٹائی پر ایک نیم برہنہ معمر جوگیوں کا آسن لگائے بیٹھا ہے۔ اس کی بیٹھک سے، اس کے گنجے سر سے، اس کی ادھ کُھلی آنکھوں سے، اس کے سانولے ملائم جسم سے، اس کے چہرے کے ہر خط سے ایک پرسکون اطمینان، ایک بے فکر تیقن مترشح تھا کہ جس مقام پر دنیا نے اسے بٹھا دیا ہے، اب بڑے سے بڑا زلزلہ بھی اسے وہاں سے نہیں گرا سکتا۔۔۔ اس سے کچھ دور وادی کشمیر کی ایک نوخیز کلی، جھکی ہوئی، کچھ اس بزرگ کی قربت کے احترام سے، کچھ قومی گیت کے اثر سے، کچھ اپنی شدید جوانی سے، جو اس کی کھردردی سفید ساڑی سے نکل کر قومی گیت کے علاوہ اپنی جوانی کا گیت بھی گانا چاہتی تھی، جو اس بزرگ کی قربت کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایسی تندرست اور جوان ہستی کی بھی تعظیم کرنے کی خواہش مند تھی جو اس کی نرم کلائی پکڑ کر زندگی کے دہکتے ہوئے الاؤ میں کود پڑے۔ اس کے ہلکے پیازی چہرے سے، اس کی بڑی بڑی سیاہ متحرک آنکھوں سے، اس کے کھادی کے کھردرے بلاؤز میں ڈھکے ہوئے متلاطم سینے سے ،اس معمر جوگی کے ٹھوس تیقن اور سنگین اطمینان کے تقابل میں ایک خاموش صدا تھی کہ آؤ، جس مقام پر میں اس وقت ہوں،وہاں سے کھینچ کر مجھے یا تو نیچے گرا دو یا اس سے بھی اوپر لے جاؤ۔
اس طرف ہٹ کر ہم تین بیٹھے تھے۔ میں، نگار اور شہزادہ غلام علی۔۔۔۔ میں بالکل چغد بنا بیٹھا تھا۔ بابا جی کی شخصیت سے بھی متاثر تھا اور اس پنڈتانی کے بے د اغ حسن سے بھی۔ فرش کی چمکیلی ٹائلوں نے بھی مجھے مرعوب کیا تھا۔ کبھی سوچتا تھا کہ ایسی ٹائلوں والی ایک کوٹھی مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ پھر سوچتا تھا کہ یہ پنڈتانی مجھے اور کچھ نہ کرنے دے، ایک صرف مجھے اپنی آنکھیں چوم لینے دے۔ اس کے تصور سے بدن میں تھرتھری پیدا ہوتی تو جھٹ اپنی نوکرانی کا خیال آتا جس سے تازہ تازہ مجھے کچھ وہ ہوا تھا۔ جی میں آتا کہ ان سب کو، یہاں چھوڑ کر سیدھا گھر جاؤں۔۔۔ شاید نظر بچا کر اسے اوپر غسل خانے تک لے جانے میں کامیاب ہو سکوں، مگر جب بابا جی پر نظر پڑتی اور کانوں میں قومی گیت کے پرجوش الفاظ گونجتے تو ایک دوسری تھرتھری بدن میں پیدا ہوتی اور میں سوچتا کہ کہیں سے پستول ہاتھ آجائے تو سول لائن میں جا کر انگریزوں کو مارنا شروع کردوں۔
اس چغد کے پاس نگار اور غلام علی بیٹھے تھے۔ دو محبت کرنے والے دل، جو تنہا محبت میں دھڑکتے دھڑکتے اب شاید کچھ اکتا گئے تھے اور جلدی ایک دوسرے میں محبت کے دوسرے رنگ دیکھنے کے لیے مدغم ہونا چاہتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہ بابا جی سے، اپنے مسلمہ سیاسی رہنما سے شادی کی اجازت لینے آئے تھے اور جیسا کہ ظاہر ہے ان دونوں کے دماغ میں اس وقت قومی گیت کے بجائے ان کی اپنی زندگی کا حسین ترین مگر ان سنا نغمہ گونج رہا تھا۔
گیت ختم ہوا ،بابا جی نے بڑے مشفقانہ انداز سے پنڈتانی کو ہاتھ کے اشارے سے آشیرواد دیا اور مسکراتے ہوئے نگار اور غلام علی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے بھی انھوں نے ایک نظر دیکھ لیا۔غلام علی شاید تعارف کے لیے اپنا اور نگار کا نام بتانے والا تھا مگر بابا جی کا حافظہ بلا کا تھا۔ انھوں نے فوراً ہی اپنی میٹھی آواز میں کہا،’’شہزادے ،ابھی تک تم گرفتار نہیں ہوئے؟‘‘
غلام علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ’’جی نہیں۔‘‘
بابا جی نے قلم دان سے ایک پنسل نکالی اور اس سے کھیلتے ہوئے کہنے لگے، ’’مگر میں تو سمجھتا ہوں تم گرفتار ہو چکے ہو۔‘‘
غلام علی اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ لیکن بابا جی نے فوراً ہی پنڈتانی کی طرف دیکھا اور نگار کی طرف اشارہ کرکے،’’نگار نے ہمارے شہزادے کو گرفتار کرلیا ہے۔‘‘
نگار محجوب سی ہوگئی۔ غلام علی کا منہ فرطِ حیرت سےکھلا کا کھلا رہ گیا اور پنڈتانی کے پیازی چہرے پر ایک دعائیہ چمک سی آئی۔ اس نے نگار اور غلام علی کو کچھ اس طرح دیکھا جیسے یہ کہہ رہی ہے، ’’بہت اچھا ہوا۔‘‘ بابا جی ایک بار پھر پنڈتانی کی طرف متوجہ ہوئے، ’’یہ بچے مجھ سے شادی کی اجازت لینے آئے ہیں۔۔۔ تم کب شادی کررہی ہو کمل؟‘‘
تو اس پنڈتانی کا نام کمل تھا۔ بابا جی کے اچانک سوال سے وہ بوکھلا گئی۔ اس کا پیازی چہرہ سرخ ہوگیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے جواب دیا، ’’میں تو آپ کے آشرم میں جارہی ہوں۔‘‘ ایک ہلکی سی آہ بھی ان الفاظ میں لپٹ کرباہر آئی جسے بابا جی کے ہشیار دماغ نے فوراً نوٹ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر جوگیانہ انداز میں مسکرائے اور غلام علی اور نگار سے مخاطب ہو کرکہنے لگے،’’ تو تم دونوں فیصلہ کر چکے ہو۔‘‘
دونوں نے دبی زبان میں جواب دیا، ’’جی ہاں۔‘‘
بابا جی نے اپنی سیاست بھری آنکھوں سے ان کو دیکھا،’’انسان جب فیصلے کرتا ہے تو کبھی کبھی ان کو تبدیل کردیا کرتا ہے۔‘‘
پہلی دفعہ بابا جی کی بارعب موجودگی میں غلام علی نے، اس کی الھڑ اور بیباک جوانی نے کہا،’’یہ فیصلہ اگر کسی وجہ سے تبدیل ہو جائے تو بھی اپنی جگہ پر اٹل رہے گا۔‘‘
بابا جی نے آنکھیں بند کرلیں اور جرح کے انداز میں پوچھا،’’کیوں؟‘‘
حیرت ہے کہ غلام علی بالکل نہ گھبرایا۔ شاید اس دفعہ نگارسے جو اسے پرخلوص محبت تھی وہ بول اٹھی، ’’بابا جی ہم نے ہندوستان کو آزادی دلانے کا جو فیصلہ کیا ہے، وقت کی مجبوریاں اسے تبدیل کرتی رہیں مگر جو فیصلہ ہے وہ تو اٹل ہے۔‘‘ بابا جی نے جیسا کہ میرا اب خیال ہے کہ اس موضوع پر بحث کرنا مناسب خیال نہ کیا چنانچہ وہ مسکرا دیے۔۔۔ اس مسکراہٹ کا مطلب بھی ان کی تمام مسکراہٹوں کی طرح ہر شخص نے بالکل الگ الگ سمجھا۔ اگر بابا جی سے پوچھا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا مطلب ہم سب سے بالکل مختلف بیان کرتے۔
خیر۔۔۔ اس ہزار پہلو مسکراہٹ کو اپنے پتلے ہونٹوں پر ذرا اور پھیلاتے ہوئے انھوں نے نگار سے کہا،’’نگار تم ہمارے آشرم میں آجاؤ۔۔۔ شہزادہ تو تھوڑے دنوں میں قید ہو جائے گا۔‘‘
نگار نے بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا، ’’جی اچھا۔‘‘
اس کے بعد بابا جی نے شادی کا موضوع بدل کر جلیانوالہ باغ کیمپ کی سرگرمیوں کا حال پوچھنا شروع کردیا۔ بہت دیر تک غلام علی، نگار اور کمل گرفتاریوں، رہائیوں، دودھ،لسی اور ترکاریوں کے متعلق باتیں کرتے رہے اور جو میں بالکل چغد بنا بیٹھا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بابا جی نے شادی کی اجازت دینے میں کیوں اتنی مین میخ کی ہے۔ کیا وہ غلام علی اور نگار کی محبت کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔۔۔؟ کیا انھیں غلام علی کے خلوص پرشبہ ہے؟
نگار کو انھوں نے کیا آشرم میں آنے کی اس لیے دعوت دی کہ وہاں رہ کر وہ اپنے قید ہونے والے شوہر کا غم بھول جائے گی۔۔۔؟لیکن بابا جی کے اس سوال پر’’ کمل تم کب شادی کررہی ہو؟‘‘ کمل نے کیوں کہا تھا کہ میں تو آپ کے آشرم میں جارہی ہوں۔۔۔؟ آشرم میں کیا مرد عورت شادی نہیں کرتے۔۔۔۔؟ میرا ذہن عجب مخمصے میں گرفتار تھا۔ مگر ادھر یہ گفتگو ہورہی تھی کہ لیڈی والنٹیرز کیا پانچ سو رضاکاروں کے لیے چپاتیاں وقت پر تیار کرلیتی ہیں؟ چولہے کتنے ہیں؟ اور توے کتنے بڑے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ ایک بہت بڑا چولہا بنالیا جائے اور اس پر اتنا بڑا توا رکھا جائے کہ چھ عورتیں ایک ہی وقت میں روٹیاں پکا سکیں؟
میں یہ سوچ رہا تھا کہ پنڈتانی کمل کیا آشرم میں جا کر باباجی کو بس قومی گیت اور بھجن ہی سنایا کرے گی۔ میں نے آشرم کے مرد والنٹیر دیکھے تھے۔ گر وہ سب کے سب وہاں کے قواعد کے مطابق ہر روز اشنان کرتے تھے، صبح اٹھ کر داتن کرتے تھے، باہر کھلی ہوا میں رہتے تھے، بھجن گاتے تھے،مگر ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو پھر بھی آتی تھی۔ ان میں اکثر کے دانت بدبودار تھے اور وہ جو کھلی فضا میں رہنے سے انسان پر ایک ہشاش بشاش نکھار آتا ہے،ان میں بالکل مفقود تھا۔
جھکے جھکے سے، دبے دبے سے۔۔۔ زرد چہرے،دھنسی ہوئی آنکھیں، مرعوب جسم۔۔۔ گائے کے نچڑے ہوئے تھنوں کی طرح بے حس اور بے جان۔۔۔ میں ان آشرم والوں کو جلیانوالہ باغ میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔۔۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہی مرد جن سے گھاس کی بو آتی ہے،اس پنڈتانی کو جو دودھ، شہد اور زعفران کی بنی ہے، اپنی کیچڑ بھری آنکھوں سے گھوریں گے۔ کیا یہی مرد جن کا منہ اس قدر متعفن ہوتا ہے، اس لوبان کی مہک میں لپٹی ہوئی عورت سے گفتگو کریں گے؟
لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں ہندوستان کی آزادی شاید ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ میں اس ’’شاید‘‘ کو اپنی تمام حب الوطنی اور جذبۂ آزادی کے باوجود نہ سمجھ سکا۔ کیونکہ مجھے نگار کا خیال آیا جو بالکل میرے قریب بیٹھی تھی اور بابا جی کو بتارہی تھی کہ شلجم بہت دیر میں گلتے ہیں۔۔۔ کہاں شلجم اور کہاں شادی جس کے لیے وہ اور غلام علی اجازت لینے آئے تھے۔
میں نگار اور آشرم کے متعلق سوچنے لگا۔ آشرم میں نے دیکھا نہیں تھا،مگر مجھے ایسی جگہوں سے جن کو آشرم، ودیالہ جماعت خانہ، تکیہ، یا درس گاہ کہا جائے، ہمیشہ سے نفرت ہے۔ جانے کیوں؟میں نے کئی اندھ ودیالوں اور اناتھ آشرموں کے لڑکوں اور ان کے متنظموں کو دیکھا ہے، سڑک میں قطار باندھ کرچلتے اور بھیک مانگتے ہوئے۔ میں نے جماعت خانے اور درس گاہیں دیکھی ہیں۔ ٹخنوں سے اونچا شرعی پائجامہ، بچپن ہی میں ماتھے پر محراب، جو بڑے ہیں ان کے چہرے پر گھنی داڑھی۔۔۔ جو نوخیر ہیں ان کے گالوں اور ٹھڈی پر نہایت ہی بدنما موٹے اور مہین بال۔۔۔ نماز پڑھتے جارہے ہیں لیکن ہر ایک کے چہرے پر حیوانیت۔۔۔ ایک ادھوری حیوانیت مصلے پر بیٹھی نظر آتی ہے۔
نگار عورت تھی۔ مسلمان، ہندو، سکھ یا عیسائی عورت نہیں۔۔۔ وہ صرف عورت تھی، نہیں عورت کی دعا تھی جو اپنے چاہنے والے کے لیے یا جسے وہ خود چاہتی ہے صدق دل سے مانگتی ہے۔میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بابا جی کے آشرم میں جہاں ہر روز قواعد کے مطابق دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ عورت جو خود ایک دعا ہے، کیسے اپنے ہاتھ اٹھا سکے گی۔
میں اب سوچتا ہوں تو باباجی، نگار، غلام علی، وہ خوبصورت پنڈتانی اور امرتسر کی ساری فضا جو تحریک آزادی کے رومان آفریں کیف میں لپٹی ہوئی تھی، ایک خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا خواب جو ایک بار دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے آدمی پھر دیکھے۔ بابا جی کا آشرم میں نے اب بھی نہیں دیکھا، مگر جو نفرت مجھے اس سے پہلے تھی اب بھی ہے۔وہ جگہ جہاں فطرت کے خلاف اصول بنا کر انسانوں کو ایک لکیر پرچلایا جائے، میری نظروں میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ آزادی حاصل کرنا بالکل ٹھیک ہے! اس کے حصول کے لیے آدمی مر جائے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے اگر اس غریب کو ترکاری کی طرح ٹھنڈا اور بے ضرر بنا دیا جائے تو یہی میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔
جھونپڑوں میں رہنا، تن آسانیوں سے پرہیز کرنا، خدا کی حمد گانا، قومی نعرے مارنا۔۔۔ یہ سب ٹھیک ہے ،مگر یہ کیا کہ انسان کی اس حِس کو جسے طلبِ حسن کہتے ہیں آہستہ آہستہ مردہ کردیا جائے۔ وہ انسان کیا جس میں خوبصورتی اور ہنگاموں کی تڑپ نہ رہے۔ ایسے آشرموں، مدرسوں، ودیالوں اور مولیوں کے کھیت میں کیا فرق ہے۔
دیر تک بابا جی، غلام علی اور نگار سے جلیانوالہ باغ کی جملہ سرگرمیوں کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں انھوں نے اس جوڑے کو، جو کہ ظاہر ہے کہ اپنے آنے کا مقصد بھول نہیں گیا تھا، کہا کہ وہ دوسرے روز شام کو جلیانوالہ باغ آئیں گے اور ان دونوں کو میاں بیوی بنا دیں گے۔
غلام علی اور نگار بہت خوش ہوئے۔ اس سے بڑھ کر ان کی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی کہ بابا جی خود شادی کی رسم ادا کریں گے۔ غلام علی، جیسا کہ اس نے مجھے بہت بعد میں بتایا، اس قدر خوش ہوا تھا کہ فوراً ہی سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید جو کچھ اس نے سنا ہے غلط ہے۔ کیونکہ بابا جی کے منحنی ہاتھوں کی خفیف سی جنبش بھی ایک تاریخی حادثہ بن جاتی تھی۔ اتنی بڑی ہستی ایک معمولی آدمی کی خاطر جو محض اتفاق سے کانگریس کا ڈکٹیٹر بن گیا ہے، چل کے جلیانوالہ باغ جائے اور اس کی شادی میں دلچسپی لے۔ یہ ہندوستان کے تمام اخباروں کے پہلے صفحے کی جلی سرخی تھی۔
غلام علی کا خیال تھا بابا جی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بہت مصروف آدمی ہیں لیکن اس کا یہ خیال، جس کا اظہار دراصل اس نے نفسیاتی نقطہ نگاہ سے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ ضرور آئیں، اس کی خواہش کے مطابق غلط ثابت ہوا۔۔۔ شام کے چھ بجے جلیانوالہ باغ میں جب رات کی رانی کی جھاڑیاں اپنی خوشبو کے جھونکے پھیلانے کی تیاریاں کررہی تھیں اور متعدد رضاکار دولہا دلہن کے لیے ایک چھوٹا تنبو نصب کرکے اسے چمیلی، گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجا رہے تھے،بابا جی اس قومی گیت گانے والی پنڈتانی، اپنے سیکریٹری اور لالہ ہری رام صراف کے ہم راہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے۔ ان کی آمد کی اطلاع جلیانوالہ باغ میں صرف اسی وقت پہنچی، جب صدر دروازے پر لالہ ہری رام کی ہری موٹر رکی۔
میں بھی وہیں تھا۔ لیڈی والنٹیرز ایک دوسرے تنبو میں نگار کو دلہن بنا رہی تھیں۔ غلام علی نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا۔ سارا دن وہ شہر کے کانگریسی بنیوں سے رضا کاروں کے کھانے پینے کی ضروریات کے متعلق گفتگو کرتا رہا تھا۔ اس سے فارغ ہوکر اس نے چند لمحات کے لیے نگار سے تخلیے میں کچھ بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے ماتحت افسروں سے صرف اتنا کہا تھا کہ شادی کی رسم ادا ہونے کے ساتھ ہی وہ اور نگار دونوں جھنڈا اونچا کریں گے۔
جب غلام علی کو بابا جی کی آمد کی اطلاع پہنچی تو وہ کنوئیں کے پاس کھڑا تھا۔ میں غالباً اس سے یہ کہہ رہا تھا،’’غلام علی تم جانتے ہوں یہ کنواں، جب گولی چلی تھی، لاشوں سے لبالب بھر گیا تھا۔۔۔ آج سب اس کا پانی پیتے ہیں۔۔۔ اس باغ کے جتنے پھول ہیں۔ اس کے پانی نے سینچے ہیں۔ مگر لوگ آتے ہیں اور انھیں توڑ کر لے جاتے ہیں۔۔۔ پانی کے کسی گھونٹ میں لہو کا نمک نہیں ہوتا، پھول کی کسی پتی میں خون کی لالی نہیں ہوتی۔۔۔ یہ کیا بات ہے؟‘‘
مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہ کہہ کر اپنے سامنے، اس مکان کی کھڑکی کی طرف دیکھا جس میں، کہا جاتا ہے کہ ایک نو عمر لڑکی بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی اور جنرل ڈائر کی گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ اس کے سینے سے نکلے ہوئے خون کی لکیر چونے کی عمر رسیدہ دیوار پر دھندلی ہورہی تھی۔اب خون کچھ اس قدر ارزاں ہوگیا کہ اس کے بہنے بہانے کا وہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ جلیانوالہ باغ کے خونیں حادثے کے چھ سات مہینے بعد جب میں تیسری یا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا،مارا ماسٹر ساری کلاس کو ایک دفعہ اس باغ میں لے گیا۔ اس وقت یہ باغ باغ نہیں تھا۔ اجاڑ، سنسان اور اونچی نیچی خشک زمین کا ایک ٹکڑا تھا، جس میں ہر قدم پر مٹی کے چھوٹے بڑے ڈھیلے ٹھوکریں کھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا جس پر جانے پان کی پیک کے دھبے یا کیا تھا، ہمارے ماسٹر نے اٹھا لیا تھا اور ہم سے کہا تھا۔ دیکھو اس پر ابھی تک ہمارے شہیدوں کا خون لگا ہے۔
یہ کہانی لکھ رہا ہوں اور حافظے کی تختی پر سیکڑوں چھوٹی چھوٹی باتیں ابھر رہی ہیں مگر مجھے تو غلام علی اور نگار کی شادی کا قصہ بیان کرنا ہے۔
غلام علی کو جب بابا جی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے دوڑ کر سب والنٹیر اکٹھے کیے جنہوں نے فوجی انداز میں ان کو سیلوٹ کیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ واور غلام علی مختلف کیمپوں کا چکرلگاتے رہے۔ اس دوران میں بابا جی نے، جن کی مزاحیہ حس بہت تیز تھی، لیڈی والنٹیرز اور دوسرے ورکرز سے گفتگوکرتے وقت کئی فقرے چست کیے۔
ادھر ادھر مکانوں میں جب بتیاں جلنے لگیں اور دھندلا اندھیرا سا جلیانوالہ باغ پر چھا گیا تو رضا کار لڑکیوں نے ایک آواز ہو کر بھجن گانا شروع کیا۔ چند آوازیں سریلی، باقی سب کن سری تھیں مگر ان کا مجموعی اثر بہت خوشگوار تھا۔ بابا جی آنکھیں بندکیے سن رہے تھے۔ تقریباً ایک ہزار آدمی موجود تھے،جو چبوترے کے اردگرد زمین پر بیٹھے تھے۔ بھجن گانے والی لڑکیوں کے علاوہ ہر شخص خاموش تھا۔بھجن ختم ہونے پر چند لمحات تک ایسی خاموشی طاری رہی جو ایک دم ٹوٹنے کے لیے بے قرارہو۔ چنانچہ جب بابا جی نے آنکھیں کھولیں اور اپنی میٹھی آواز میں کہا، ’’بچو، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے،میں یہاں آج آزادی کے دو دیوانوں کو ایک کرنے آیا ہوں۔‘‘ تو سارا باغ خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔
نگار دلہن بنی چبوترے کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کھادی کی ترنگی ساڑی میں بہت بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ بابا جی نے اشارے سے اسے بلایا اور غلام علی کے پاس بٹھا دیا۔ اس پر اور خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔غلام علی کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتما رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، جب اس نے نکاح کا کاغذ اپنے دوست سے لے کربابا جی کو دیا تو اس کا ہاتھ لرز گیا۔ چبوترے پر ایک مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ انھوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو ایسے موقعوں پر پڑھا کرتے ہیں۔ بابا جی نے آنکھیں بند کرلیں۔ ایجاب و قبول ختم ہوا تو انھوں نے اپنے مخصوص انداز میں دولھا دلہن کو آشیرواد دی اور جب چھوہاروں کی بارش شروع ہوئی تو انھوں نے بچوں کی طرح جھپٹ جھپٹ کر دس پندرہ چھوہارے اکٹھے کرکے اپنے پاس رکھ لیے۔
نگار کی ایک ہندو سہیلی نے شرمیلی مسکراہٹ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا غلام علی کو دی اور اس سے کچھ کہا۔ غلام علی نے ڈبیا کھولی اور نگار کی سیدھی مانگ میں سیندور بھر دیا۔ جلیانوالہ باغ کی خنک فضا ایک بار پھر تالیوں کی تیز آواز سے گونج اٹھی۔
بابا جی اس شور میں اٹھے۔ ہجوم ایک دم خاموش ہوگیا۔
رات کی رانی اور چمیلی کی ملی جلی سوندھی سوندھی خوشبو، شام کی ہلکی پھلکی ہوا میں تیر رہی تھی، بہت سہانا سماں تھا، بابا جی کی آواز آج اور بھی میٹھی تھی۔ غلام علی اور نگار کی شادی پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرنے کے بعد انھوں نے کہا:یہ دونوں بچے اب زیادہ تندہی اور خلوص سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ کیونکہ شادی کا صحیح مقصد مرد اور عورت کی پرخلوص دوستی ہے۔ ایک دوسرے کے دوست بن کر غلام علی اور نگار یکجہتی سے سوراج کے لیے کوشش کرسکتے ہیں۔ یورپ میں ایسی کئی شادیاں ہوتی ہیں جن کا مطلب دوستی اور صرف دوستی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ قابل احترام ہیں جو اپنی زندگی سے شہوت نکال پھینکتے ہیں۔
بابا جی دیر تک شادی کے متعلق اپنے عقیدے کا اظہار کرتے رہے۔ ان کا ایمان تھا کہ صحیح مزا صرف اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا تعلق صرف جسمانی نہ ہو۔ عورت اور مرد کا شہوانی رشتہ ان کے نزدیک اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں آدمی کھاتے ہیں، اپنے ذائقے کی حس کو خوش کرنے کے لیےلیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنا انسانی فرض ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے ۔اصل میں صرف یہی لوگ ہیں جو خوردونوش کے صحیح قوانین جانتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف اس لیے شادی کرتے ہیں کہ انھیں شادی کے مطہر جذبے کی حقیقت اور اس رشتے کی تقدیس معلوم ہو،حقیقی معنوں میں ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
بابا جی نے اپنے اس عقیدے کو کچھ اس وضاحت، کچھ ایسے نرم و نازک خلوص سے بیان کیا کہ سننے والوں کے لیے ایک بالکل نئی دنیا کے دروازے کھل گئے۔ میں خود بہت متاثر ہوا۔ غلام علی جو میرے سامنے بیٹھا تھا، بابا جی کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو جیسے پی رہا تھا۔ بابا جی نے جب بولنا بند کیا تو اس نے نگار سے کچھ کہا۔ اس کے بعد اٹھ کر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں یہ اعلان کیا،’’میری اور نگار کی شادی اسی قسم کی آدرش شادی ہوگی، جب تک ہندوستان کو سوراج نہیں ملتا،میرا اور نگار کا رشتہ بالکل دوستوں جیسا ہوگا۔۔۔‘‘
جلیانوالہ باغ کی خنک فضا دیر تک تالیوں کے بے پناہ شور سے گونجتی رہی۔ شہزادہ غلام علی جذباتی ہوگیا۔ اس کے کشمیری چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگیں۔ جذبات کی اسی دوڑ میں اس نے نگار کو بلند آواز میں مخاطب کیا، ’’نگار! تم ایک غلام بچے کی ماں بنو۔۔۔ کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا؟‘‘ نگار جو کچھ شادی ہونے پر اور کچھ بابا جی کی تقریر سن کر بوکھلائی ہوئی تھی، یہ کڑک سوال سن کر اور بھی بوکھلا گئی۔ صرف اتنا کہہ سکی، ’’جی۔۔۔؟ جی نہیں۔‘‘
ہجوم نے پھر تالیاں پیٹیں اور غلام علی اور زیادہ جذباتی ہوگیا۔ نگار کو غلام بچے کی شرمندگی سے بچا کر وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ بہک گیا اور اصل موضوع سے ہٹ کر آزادی حاصل کرنے کی پیچ دار گلیوں میں جا نکلا۔ ایک گھنٹے تک وہ جذبات بھری آواز میں بولتا رہا۔ اچانک اس کی نظر نگار پر پڑی۔ جانے کیا ہوا۔۔۔ ایک دم اس کی قوت گویائی جواب دے گئی۔ جیسے آدمی شراب کے نشے میں بغیر کسی حساب کے نوٹ نکالتا جائے اور ایک دم بٹوہ خالی پائے۔ اپنی تقریر کا بٹوہ خالی پا کر غلام علی کو کافی الجھن ہوئی مگر اس نے فوراً ہی بابا جی کی طرف دیکھا اور جھک کرکہا،’’بابا جی۔۔۔ ہم دونوں کو آپ کا آشیرواد چاہیے کہ جس بات کا ہم نے عہد کیا ہے، اس پر پورے رہیں۔‘‘
دوسرے روز صبح چھ بجے شہزادہ غلام علی کو گرفتار کرلیا گیا۔ کیونکہ اس تقریر میں جو اس نے سوراج ملنے تک بچہ پیدا نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد کی تھی، انگریزوں کا تختہ الٹنے کی دھمکی بھی تھی۔گرفتار ہونے کے چند روز بعد غلام علی کو آٹھ مہینے کی قید ہوئی اور ملتان جیل بھیج دیا گیا۔ وہ امرتسر کا اکیالیسواں ڈکٹیٹر تھا اور شاید چالیس ہزارواں سیاسی قیدی۔ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، اس تحریک میں قید ہونے والے لوگوں کی تعداد اخباروں نے چالیس ہزار ہی بتائی تھی۔
عام خیال تھا کہ آزادی کی منزل اب صرف دو ہاتھ ہی دور ہے۔ لیکن فرنگی سیاست دانوں نے اس تحریک کا دودھ ابلنے دیا اور جب ہندوستان کے بڑے لیڈروں کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہ ہوا تو یہ تحریک ٹھنڈی لسی میں تبدیل ہوگئی۔آزادی کے دیوانے جیلوں سے باہر نکلے تو قید کی صعوبتیں بھولنے اور اپنے بگڑے ہوئے کاروبار سنوارنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادہ غلام علی سات مہینے کے بعد ہی باہر آگیا تھا۔ گو اس وقت پہلا سا جوش نہیں تھا،پھر بھی امرتسر کے اسٹیشن پر لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے اعزاز میں تین چار دعوتیں اور جلسے بھی ہوئے۔ میں ان سب میں شریک تھا مگر یہ محفلیں بالکل پھیکی تھیں۔ لوگوں پر اب ایک عجیب قسم کی تھکاوٹ طاری تھی جیسے ایک لمبی دوڑ میں اچانک دوڑنے والوں سے کہہ دیا گیا تھا، ’’ٹھہرو، یہ دوڑ پھر سے شروع ہوگی۔‘‘ اور اب جیسے یہ دوڑنے والے کچھ دیر ہانپنے کے بعد دوڑ کے مقام آغاز کی طرف بڑی بے دلی کے ساتھ واپس آرہے تھے۔
کئی برس گزر گئے۔۔۔ یہ بے کیف تھکاوٹ ہندوستان سے دور نہ ہوئی تھی۔ میری دنیا میں چھوٹے موٹے کئی انقلاب آئے۔ داڑھی مونچھ اگی، کالج میں داخل ہوا، ایف اے میں دوبارہ فیل ہوا،والد انتقال کرگئے، روزی کی تلاش میں ادھر ادھر پریشان ہوا، ایک تھرڈ کلاس اخبار میں مترجم کی حیثیت سے نوکری کی، یہاں سے جی گھبرایا تو ایک بار پھر تعلیم حاصل کرنے کا خیال آیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہوا اور تین ہی مہینے بعد دق کا مریض ہو کرکشمیر کے دیہاتوں میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ وہاں سے لوٹ کر بمبئی کا رخ کیا۔ یہاں دو برسوں میں تین ہندو مسلم فساد دیکھے۔ جی گھبرایا تو دلی چلا گیا۔ وہاں بمبئی کے مقابلے میں ہر چیز سست رفتار دیکھی۔ کہیں حرکت نظر بھی آئی تو اس میں ایک زنانہ پن محسوس ہوا۔ آخر یہی سوچا کہ بمبئی اچھا ہے۔ کیا ہوا ساتھ والے ہمسائے کو ہمارا نام تک پوچھنے کی فرصت نہیں۔ جہاں لوگوں کو فرصت ہوتی ہے،وہاں ریا کاریاں اور چال بازیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ دلی میں دو برس ٹھنڈی زندگی بسر کرنے کے بعد سدا متحرک بمبئی چلا آیا۔
گھر سے نکلے اب آٹھ برس ہو چلے تھے۔ دوست احباب اور امرتسر کی سڑکیں، گلیاں کس حالت میں ہیں، اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا، کسی سے خط و کتابت ہی نہیں تھی جو پتہ چلتا۔ دراصل مجھے ان آٹھ برسوں میں اپنے مستقبل کی طرف سے کچھ بے پروائی سی ہوگئی تھی۔۔۔ کون بیتے ہوئے دنوں کے متعلق سوچے۔ جو آٹھ برس پہلے خرچ ہو چکا ہے،اس کا اب احساس کرنے سے فائدہ۔۔۔؟ زندگی کے روپے میں وہی پائی زیادہ اہم ہے جسے تم آج خرچنا چاہتے ہو یا جس پرکل کسی کی آنکھ ہے۔
آج سے چھ برس پہلے کی بات کررہا ہوں، جب زندگی کے روپے اور چاندی کے روپے سے، جس پر بادشاہ سلامت کی چھاپ ہوتی ہے، پائی خارج نہیں ہوئی تھی۔ میں اتنا زیادہ قلاش نہیں تھاکیونکہ فورٹ میں اپنے پاؤں کے لیے ایک قیمتی شو خریدنے جارہا تھا۔آرمی اینڈ نیوی اسٹور کے اس طرف ہاربنی روڈ پر جوتوں کی ایک دکان ہے جس کی نمائشی الماریاں مجھے بہت دیر سے اس طرف کھینچ رہی تھیں۔ میرا حافظہ بہت کمزور ہے ،چنانچہ یہ دکان ڈھونڈنے میں کافی وقت صرف ہوگیا۔
یوں تو میں اپنے لیے ایک قیمتی شو خریدنے آیا تھا مگر جیسا کہ میری عادت ہے، دوسری دکانوں میں سجی ہوئی چیزیں دیکھنے میں مصروف ہوگیا۔ ایک اسٹور میں سگریٹ کیس دیکھے، دوسرے میں پائپ، اسی طرح فٹ پاتھ پر ٹہلتا ہوا جوتوں کی ایک چھوٹی سی دکان کے پاس آیا اور اس کے اندر چلا گیا کہ چلو یہیں سے خرید لیتے ہیں، دکاندار نے میرا استقبال کیا اور پوچھا،’’کیا مانگتا ہے صاحب۔‘‘
میں نے تھوڑی دیر یاد کیا کہ مجھے کیا چاہیے، ’’ہاں۔۔۔ کریپ سول شو۔‘‘
’’ادھر نہیں رکھتا ہم۔‘‘
مون سون قریب تھی۔ میں نے سوچا گم بوٹ ہی خرید لوں،’’گم بوٹ نکالو۔‘‘
’’باجو والے کی دکان سے ملیں گے۔۔۔ ربڑ کی کئی چیز ہم ادھر نہیں رکھتا۔‘‘
میں نے ایسے ہی پوچھا، ’’کیوں؟‘‘
’’سیٹھ کی مرضی!‘‘
یہ مختصر مگر جامع جواب سن کر میں دکان سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک خوش پوش آدمی پر میری نظر پڑی جو باہر فٹ پاتھ پر ایک بچہ گود میں اٹھائے پھل والے سے سنگترہ خرید رہا تھا۔ میں باہر نکلا اور وہ دکان کی طرف مڑا، ’’ارے۔۔۔ غلام علی۔۔۔‘‘
’’سعادت !‘‘
یہ کہہ کر اس نے بچے سمیت مجھے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ بچے کو یہ حرکت ناگوار معلوم ہوئی، چنانچہ اس نے رونا شروع کردیا۔ غلام علی نے اس آدمی کو بلایا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ ربڑ کی کوئی چیز ادھر ہم نہیں رکھتا اور اسے بچہ دے کر کہا ’’جاؤ اسے گھر لے جاؤ۔‘‘ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ’’کتنی دیر کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں۔‘‘
میں نے غلام علی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔۔۔ وہ کج کلاہی، وہ ہلکا سا غنڈا پن جو اس کی امتیازی شان تھا۔ اب بالکل مفقود تھا۔۔۔ میرے سامنے آتشیں تقریریں کرنے والے کھادی پوش نوجوان کی جگہ ایک گھریلو قسم کا عام انسان کھڑا تھا۔۔۔ مجھے اس کی وہ آخری تقریر یاد آئی، جب اس نے جلیانوالہ باغ کی خنک فضا کو ان گرم الفاظ سے مرتعش کیا تھا، ’’نگار۔۔۔ تم ایک غلام بچے کی ماں بنو۔۔۔ کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا۔۔۔‘‘ فوراً ہی مجھے اس بچے کا خیال آیاجو غلام علی کی گود میں تھا۔ میں اس سے یہ پوچھا،’’یہ بچہ کس کا ہے؟‘‘ غلام علی نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا،’’میرا۔۔۔ اس سے بڑا ایک اور بھی ہے۔۔۔ کہو، تم نے کتنے پیدا کیے۔‘‘
ایک لحظے کے لیے مجھے محسوس ہوا جیسے غلام علی کے بجائے کوئی اور ہل بول رہا ہے۔ میرے دماغ میں سیکڑوں خیال اوپر تلے گرتے گئے۔ کیا غلام علی اپنی قسم بالکل بھول چکا ہے؟کیا اس کی سیاسی زندگی اس سے قطعاً علیحدہ ہو چکی ہے؟ ہندوستان کو آزادی دلانے کا وہ جوش، وہ ولولہ کہاں گیا؟ اس بے ریش و بروت للکار کا کیا ہوا۔۔۔؟ نگار کہاں تھی۔۔۔؟کیا اس نے دو غلام بچوں کی ماں بننا گوارا کیا۔۔۔؟ شاید وہ مرچکی ہو۔ہو سکتا ہے، غلام علی نے دوسری شادی کرلی ہو۔
’’کیا سوچ رہے ہو۔۔۔ کچھ باتیں کرو۔ اتنی دیر کے بعد ملے ہیں۔‘‘ غلام علی نے میرے کاندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔
میں شاید خاموش ہوگیا تھا۔ ایک دم چونکا اور ایک لمبی ’’ہاں‘‘ کرکے سوچنے لگا کہ گفتگو کیسے شروع کروں۔ لیکن غلام علی نے میرا انتظار نہ کیا اور بولنا شروع کردیا، ’’یہ دکان میری ہے۔ دو برس سے میں یہاں بمبئی میں ہوں۔ بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے۔ تین چار سو مہینے کے بچ جاتے ہیں۔ تم کیا کررہے ہو۔ سنا ہے کہ بہت بڑے افسانہ نویس بن گئے ہو۔ یاد ہے ہم ایک دفعہ یہاں بھاگ کے آئے تھے۔۔۔ لیکن یار عجیب بات ہے،اس بمبئی اور اس بمبئی میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ چھوٹی تھی اور یہ بڑی ہے۔‘‘
اتنے میں ایک گاہک آیا، جسے ٹینس شو چاہیے تھا۔ غلام علی نے اس سے کہا،’’ربڑ کا مال اِدھر نہیں ملتا۔ بازو کی دکان میں چلے جائیے۔‘‘
گاہک چلا گیا تو میں نے غلام سے پوچھا، ’’ربڑ کا مال تم کیوں نہیں رکھتے؟ میں بھی یہاں کریپ سول شو لینے آیا تھا۔‘‘
یہ سوال میں نے یونہی کیا تھالیکن غلام علی کا چہرہ ایک دم بے رونق ہوگیا۔
دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، ’’مجھے پسند نہیں۔‘‘
’’کیا پسند نہیں؟‘‘
’’یہی ربڑ۔۔۔ ربڑ کی بنی ہوئی چیزیں۔‘‘یہ کہہ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جب ناکام رہا تو زور سے خشک سا قہقہہ لگایا، ’’میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہے تو بالکل واہیات سی چیز، لیکن۔۔۔ لیکن میری زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔‘‘
تفکر کی گہرائی غلام علی کے چہرے پر پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں جن میں ابھی تک کھلنڈرا پن موجود تھا، ایک لحظے کے لیے دھندلی ہوئیں لیکن پھر چمک اٹھیں،’’بکواس تھی یار وہ زندگی۔۔۔ سچ کہتا ہوں سعادت میں وہ دن بالکل بھول چکا ہوں۔ جب میرے دماغ پر لیڈری سوار تھی۔ چار پانچ برس سے اب بڑے سکون میں ہوں۔ بیوی ہے ،بچے ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔‘‘
اللہ کے فضل و کرم سے متاثر ہو کر غلام علی نے بزنس کا ذکر شروع کردیا کہ کتنے سرمائےسے اس نے کام شروع کیا تھا، ایک برس میں کتنا فائدہ ہوا، اب بنک میں اس کا کتنا روپیہ ہے۔ میں نے اسے درمیان میں ٹوکا اور کہا،’’ لیکن تم نے کسی واہیات چیز کا ذکر کیا تھا جس کا تمہاری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔‘‘
ایک بار پھر غلام علی کا چہرہ بے رونق ہوگیا۔ اس نے ایک لمبی ہاں کی اور جواب دیا،’’گہرا تعلق تھا۔۔۔ شکر ہے کہ اب نہیں ہے۔۔۔ لیکن مجھے ساری داستان سنانی پڑے گی۔‘‘
اتنے میں اس کا نوکر آگیا۔ دکان اس کے سپرد کرکے وہ مجھے اندر اپنے کمرے میں لے گیا،جہاں بیٹھ کر اس نے مجھے اطمینان سے بتایا کہ اسے ربڑ کی چیزوں سے کیوں نفرت پیدا ہوئی۔
’’میری سیاسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے متعلق تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرا کیریکٹر کیسا تھا، یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ ہم دونوں قریب قریب ایک جیسے ہی تھے۔ میرا مطلب ہے ہمارے ماں باپ کسی سے فخریہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لڑکے بے عیب ہیں۔ معلوم نہیں میں تم سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ لیکن شاید تم سمجھ گئے ہو کہ میں کوئی مضبوط کیریکٹر کا مالک نہیں تھا۔ مجھے شوق تھا کہ میں کچھ کروں۔ سیاست سے مجھے اسی لیے دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کرکہتا ہوں کہ میں جھوٹا نہیں تھا۔ وطن کے لیے میں جان بھی دے دیتا۔ اب بھی حاضر ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں۔۔۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان کی سیاست، اس کے لیڈر سب ناپختہ ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں تھا۔ ایک لہر اٹھتی ہے، اس میں جوش، زور، شورسبھی ہوتا ہےلیکن فوراً ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ لہر پیدا کی جاتی ہے، خود بخود نہیں اٹھتی۔۔۔ لیکن شاید میں تمہیں اچھی طرح سمجھا نہیں سکا۔‘‘
غلام علی کے خیالات میں بہت الجھاؤ تھا۔ میں نے اسے سگریٹ دیا،اسے سلگا کر اس نے زور سے تین کش لیے اور کہا،’’تمہارا کیا خیال ہے۔۔۔ کیا ہندوستان کی ہر کوشش جو اس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کی ہے، غیر فطری نہیں۔۔۔ کوشش نہیں۔۔۔ میرا مطلب ہے اس کا انجام کیا ہر بار غیر فطری نہیں ہوتا رہا۔۔۔ ہمیں کیوں آزادی نہیں ملتی۔۔۔ کیا ہم سب نامرد ہیں؟ نہیں، ہم سب مرد ہیں۔ لیکن ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہماری قوت کا ہاتھ آزادی تک پہنچنے ہی نہیں پاتا۔‘‘
میں نے اس سے پوچھا،’’تمہارا مطلب ہے آزادی اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل ہے۔‘‘ غلام علی کی آنکھیں چمک اٹھیں، ’’بالکل۔۔۔ لیکن یہ کوئی پکی دیوار نہیں ہے، کوئی ٹھوس چٹان نہیں ہے۔ ایک پتلی سی جھلی ہے۔۔۔ ہماری اپنی سیاست کی، ہماری مصنوعی زندگی کی جہاں لوگ دوسروں کو دھوکا دینے کے علاوہ اپنے آپ سے بھی فریب کرتے ہیں۔‘‘
اس کے خیالات بدستور الجھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ اپنے گزشتہ تجربوں کو اپنے دماغ میں تازہ کررہا تھا۔ سگریٹ بجھا کر اس نے میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، ’’انسان جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ نیک کام کرنے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ انسان اپنا سر منڈائے، گیروے کپڑے پہنے یا بدن پر راکھ ملے، تم کہو گے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن میں کہتاہو ں اس کی اس مرضی ہی سے، اس کی اس نرالی چیز ہی سے گمراہی پھیلتی ہے۔ یہ لوگ اونچے ہو کر انسان کی فطری کمزوریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں کہ ان کے کردار، ان کے خیالات اور عقیدے تو ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، لیکن ان کے منڈے ہوئے سر، ان کے بدن کی راکھ اور ان کے گیردے کپڑے سادہ لوح انسانوں کے دماغ میں رہ جائیں گے۔‘‘
غلام علی زیادہ جوش میں آگیا،’’دنیا میں اتنے مصلح پیدا ہوئے ہیں، ان کی تعلیم تو لوگ بھول چکے ہیں، لیکن صلیبیں، دھاگے، داڑھیاں، کڑے اور بغلوں کے بال رہ گئے ہیں۔۔۔ ایک ہزار برس پہلے جو لوگ یہاں بستے تھے،ہم ان سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آج کے مصلح کیوں خیال نہیں کرتے کہ وہ انسان کی شکل مسخ کررہے ہیں۔ جی میں کئی دفعہ آتا ہےبلند آواز میں چلانا شروع کردوں۔۔۔ خدا کے لیے انسان کو انسان رہنے دو،اس کی صورت کو تم بگاڑ چکے ہو، ٹھیک ہے۔۔۔ اب اس کے حال پر رحم کرو۔۔۔ تم اس کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن وہ غریب اپنی انسانیت بھی کھو رہا ہے۔۔۔ سعادت، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے، میں نے جو محسوس کیا ہے، وہی کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر کوئی چیز درست اور صحیح نہیں ہے۔۔۔ میں نے دو برس، پورے دو برس دماغ کے ساتھ کئی کشتیاں لڑی ہیں۔ میں نے اپنے دل، اپنے ضمیر، اپنے جسم، اپنے روئیں روئیں سے بحث کی ہے۔ مگر اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے۔ نفس ہزاروں میں ایک دو آدمی ماریں۔ سب نے اپنا نفس مارلیا تو میں پوچھتا ہوں یہ کشتہ کام کس کے آئے گا؟‘‘
یہاں تک کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ لیا اور اسے سلگانے میں ساری تیلی جلا کر گردن کو ایک خفیف سا جھٹکا دیا،’’ کچھ نہیں سعادت۔۔۔ تم نہیں جانتے۔ ۔۔میں نے کتنی روحانی اور جسمانی تکلیف اٹھائی ہے ،لیکن فطرت کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گا، اسے تکلیف برداشت کرنی ہی ہوگی۔۔۔ میں نے اس روز۔۔۔ تمہیں یاد ہوگا وہ دن۔۔۔ جلیانوالہ باغ میں اس بات کا اعلان کرکے کہ نگار اورمیں غلام بچے پیدا نہیں کریں گے، ایک عجیب قسم کی برقی مسرت محسوس کی تھی۔۔۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ اس اعلان کے بعد میرا سر اونچا ہو کر آسمان کے ساتھ جا لگا ہے۔ لیکن جیل سے واپس آنے کے بعد مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا تکلیف دہ۔۔۔ بہت ہی اذیت رساں احساس ہونے لگا کہ میں نے اپنے جسم کا اپنی روح کا ایک بہت ہی ضروری حصہ مفلوج کردیا ہے۔۔۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی زندگی کے باغ کا سب سے حسین پھول مسل ڈالا ہے۔۔۔ شروع شروع میں اس خیال سے مجھے ایک عجیب قسم کا تسلی بخش فخر محسوس ہوتا رہا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے جو دوسروں سے نہیں ہوسکتا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب میرے شعور کے مسام کھلنے لگے تو حقیقت اپنی تمام تلخیوں سمیت میرے رگ و ریشے میں رچنے لگی۔جیل سے واپس آنے پر میں نگار سے ملا۔۔۔ ہسپتال چھوڑ کر وہ بابا جی کے آشرم میں چلی گئی تھی۔۔۔ سات مہینے کی قید کے بعد جب میں اس سے ملا تو اس کی بدلی ہوئی رنگت، اس کی تبدیل شدہ جسمانی اور دماغی کیفیت دیکھ کر میں نے خیال کیاشاید میری نظروں نے دھوکا کھایا ہے۔ لیکن ایک برس گزرنے کے بعد۔۔۔ ایک برس اس کے ساتھ۔۔۔‘‘
غلام علی کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ پیدا ہوئی، ’’ہاں، ایک برس اس کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کا غم بھی وہی ہے جو میراہے۔۔۔ لیکن وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی ہے، نہ میں اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ہم دونوں اپنے عہد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ایک برس میں سیاسی جوش آہستہ آہستہ ٹھنڈاہو چکا تھا۔ کھادی کے لباس اور ترنگے جھنڈوں میں اب وہ پہلی سی کشش باقی نہ رہی تھی۔۔۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ اگر کبھی بلند ہوتا بھی تا تو اس میں وہ شان نظر نہیں آتی تھی۔۔۔ جلیانوالہ باغ میں ایک تنبو بھی نہیں تھا۔۔۔ پرانے کیمپوں کے کھونٹے کہیں کہیں گڑے نظر آتے تھے۔۔۔ خون سے سیاست کی حرارت قریب قریب نکل چکی تھی۔۔۔ میں اب زیادہ وقت گھر ہی میں رہتا تھا، اپنی بیوی کے پاس۔۔۔‘‘ ایک بار پھر غلام علی کے ہونٹوں پر وہی زخمی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوگیا۔ میں بھی چپ رہا، کیونکہ میں اس کے خیالات کا تسلسل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔
چند لمحات کے بعد اس نے اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا اور سگرٹ بجھا کر کہنے لگا، ’’ہم دونوں ایک عجیب قسم کی لعنت میں گرفتار تھے۔۔۔ نگار سے مجھے جتنی محبت ہے۔ تم اس سے واقف ہو۔۔۔ میں سوچنے لگا۔ یہ محبت کیا ہے۔۔۔؟ میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں تو کیوں اس کے رد عمل کو اپنی معراج پر پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا۔۔۔ میں کیوں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا۔۔۔ مجھے نگار کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ایک روز جب کہ شاید میں بالکل صحیح حالت میں تھا، میرا مطلب ہے جیسا کہ ہر انسان کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے انھیں چوم لیا۔۔۔ وہ میرے بازوؤں میں تھی۔۔۔ یوں کہو کہ ایک کپکپی تھی جو میرے بازوؤں میں تھی۔ قریب تھا کہ میری روح اپنے پرچھڑا کر پھڑپھڑاتی ہوئی اونچے آسمان کی طرف اڑ جائے کہ میں نے۔۔۔ کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور قید کردیا۔۔۔ اس کے بعد بہت دیر تک۔۔۔ کئی دنوں تک اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرے اس فعل سے۔۔۔ میرے اس بہادرانہ کارنامے سے میری روح کو ایسی لذت ملی ہے جس سے بہت کم انسان آشنا ہیں۔۔۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس میں ناکام رہا اور اس ناکامی نے جسے میں ایک بہت بڑی کامیابی سمجھنا چاہتا تھا۔۔۔ خدا کی قسم یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں ایسا سمجھوں ،مجھے دنیا کا سب سے زیادہ دکھی انسان بنا دیا۔۔۔ لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو، انسان حیلے بہانے تلاش کرلیتا ہے، میں نے بھی ایک راستہ نکال لیا۔ ہم دونوں سوکھ رہے تھے۔۔۔ اندر ہی اندر ہماری تمام لطافتوں پر پپڑی جم رہی تھی۔۔۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر بن رہے تھے۔۔۔ میں نے سوچا۔۔۔ بہت دنوں کے غور و فکر کے بعد ہم اپنے عہد پر قائم رہ کر بھی۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ’’ نگار غلام بچے پیدا نہیں کرے گی۔‘‘
یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر تیسری بار وہ زخمی مسکراہٹ پیدا ہوئی،لیکن فوراً ہی ایک بلند قہقہے میں تبدیل ہوگئی، جس میں تکلیف دہ احساس کی چبھن نمایاں تھی۔ پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو کروہ کہنے لگا، ’’ہماری ازواجی زندگی کا یہ عجیب و غریب دور شروع ہوا۔۔۔ اندھے کو جیسے ایک آنکھ مل گئی۔۔۔ میں ایک دم دیکھنے لگا لیکن یہ بصارت تھوڑی دیر ہی کے بعد دھندلی ہونے لگی۔۔۔ پہلے پہل تو یہی خیال تھا۔ غلام علی موزوں الفاظ تلاش کرنے لگا،’’پہلے پہل تو ہم مطمئن تھے۔ میرا مطلب ہے شروع شروع میں ہمیں اس کا قطعاً خیال نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نامطمئن ہو جائیں گے۔۔۔ یعنی ایک آنکھ تقاضا کرنے لگی کہ دوسری آنکھ بھی ہو۔۔۔ آغاز میں ہم دونوں نے محسوس کیا تھا جیسے ہم صحت مند ہورہے ہیں، ہماری تندرستی بڑھ رہی ہے۔۔۔ نگار کا چہرہ نکھر گیا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگئی تھی، میرے اعضا سے بھی خشک سا تناؤ دور ہوگیا تھا جو پہلے مجھے تکلیف دیا کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم دونوں پر عجیب قسم کی مردنی چھانے لگی۔۔۔ ایک برس ہی میں ہم دونوں ربڑ کے پتلے سے بن گئے۔۔۔ میرا احساس زیادہ شدید تھا۔۔۔ تم یقین نہیں کرو گے، لیکن خدا کی قسم اس وقت جب میں بازو کا گوشت چٹکی میں لیتا تو بالکل ربڑ معلوم ہوتا۔۔۔ ایسا لگتا تھا کہ اندر خون کی نسیں نہیں ہیں۔
نگار کی حالت مجھ سے، جہاں تک میرا خیال ہے مختلف تھی۔ اس کے سوچنے کا زاویہ اور تھا، وہ ماں بننا چاہتی تھی۔۔۔ گلی میں جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے بہت سی آہیں چھپ چھپ کر اپنے سینے کے اندر دفن کرنا پڑتی تھیں۔ لیکن مجھے بچوں کا کوئی خیال نہیں تھا، بچے نہ ہوئے تو کیا ہے، دنیا میں لاکھوں انسان موجود ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔۔۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے عہد پر قائم ہوں۔۔۔ اس سے تسکین تو کافی ہو جاتی تھی مگر میرے ذہن پر جب ربڑ کا مہین مہین جالا تننے لگا تو میری گھبراہٹ بڑھ گئی۔۔۔ میں ہر وقت سوچنے لگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے دماغ کے ساتھ ربڑ کالمس چمٹ گیا۔ روٹی کھاتا تو لقمے دانتوں کے نیچے کچکچانے لگتے۔‘‘
یہ کہتے ہوئے غلام علی کو پھریری آگئی، ’’بہت ہی واہیات اور غلط چیز تھی۔۔۔ انگلیوں میں ہرقت جیسے صابن سا لگا ہے۔۔۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوگئی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری روح کا سارا رس نچڑ گیا ہے اور اس چھلکا سا باقی رہ گیا ہے، استعمال شدہ۔۔۔ استعمال شدہ۔۔۔‘‘ غلام علی ہنسنے لگا۔ ’’شکر ہے کہ وہ لعنت دور ہوئی۔۔۔ لیکن سعادت، کن اذیتوں کے بعد۔۔۔ زندگی بالکل سوکھے ہوئے چھیچھڑے کی شکل اختیار کرگئی تھی۔۔۔ ساری حسیں مردہ ہوگئی تھیں لیکن لمس کی حس غیر فطری حد تک تیز ہوگئی تھی۔۔۔ تیز نہیں۔۔۔ اس کا صرف ایک رخ ہوگیا تھا۔۔۔ لڑکی میں، شیشے میں، لوہے میں، کاغذ میں، پتھر میں ہر جگہ ربڑ کی وہ مردہ، وہ ابکائی بھری ملائمی!!
یہ عذاب اور بھی شدید ہو جاتا جب میں اس کی وجہ کا خیال کرتا۔۔۔ میں دو انگلیوں سے اس لعنت کو اٹھا کرپھینک سکتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ عذاب کے اس سمندر میں مجھے ایک چھوٹا سا تنکا مل جائے جس کی مدد سے میں کنارے لگ جاؤں۔۔۔ بہت دیر تک میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن ایک روز جب کوٹھے پر دھوپ میں ایک مذہبی کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھ کیا رہا تھا۔۔۔ ایسے ہی سرسری نظرسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک حدیث پر پڑی۔۔۔ خوشی سے اچھل پڑا۔۔۔ سہارا میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ میں نے بار بار وہ سطریں پڑھیں،میری خشک زندگی جیسے سراب ہونے لگی۔۔۔ لکھا تھا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے لیے بچے پیدا کرنے لازم ہیں۔۔۔ صرف اسی حالت میں ان کی پیدائش روکنے کی اجازت ہے۔ جب والدین کی زندگی خطرے میں ہو۔۔۔ میں نے دو انگلیوں سے اس لعنت کو اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا۔‘‘یہ کہہ وہ بچوں کی طرح مسکرانے لگا، میں بھی مسکرا دیا، کیونکہ اس نے دو انگلیوں سے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر ایک طرف ایسے پھینکا تھا جیسے وہ کوئی نہایت ہی مکروہ چیز ہے۔
مسکراتے مسکراتے غلام علی دفعتاً سنجیدہ ہوگیا، ’’مجھے معلوم ہے سعادت۔۔۔ میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے تم اس کا افسانہ بنا دو گے۔۔۔ لیکن دیکھو میرا مذاق مت اڑانا۔۔۔ خدا کی قسم میں نے جوکچھ محسوس کیا تھا وہی تم سے کہا ہے۔۔۔ میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے،وہ یہ ہے کہ فطرت کی خلاف ورزی ہرگز ہرگز بہادری نہیں۔۔۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں کہ تم فاقہ کشی کرتے کرتے مر جاؤ، یا زندہ رہو۔۔۔ قبر کھو دکر اس میں گڑ جانا اور کئی کئی دن اس کے اندر دم سادھے رکھنا، نوکیلی کیلوں کے بستر پر مہینوں لیٹے رہنا، ایک ہاتھ برسوں اوپر اٹھائے رکھنا، حتیٰ کہ وہ سوکھ سوکھ کر لکڑی ہو جائے۔۔۔ ایسے مداری پنے سے خدا مل سکتا ہے نہ سوراج۔۔۔ اور میں تو سمجھتا ہوں ہندوستان کو سوراج صرف اس لیے نہیں مل رہا کہ یہاں مداری زیادہ ہیں اور لیڈر کم۔۔۔ جو ہیں وہ قوانین فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔۔۔ ایمان اور صاف دلی کا برتھ کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے سیاست ایجاد کرلی ہے اور یہی سیاست ہے جس نے آزادی کے رحم کا منہ بند کردیا ہے۔۔۔‘‘
غلام علی اس کے آگے بھی کچھ کہنے والا تھا کہ اس کا نوکر اندر داخل ہوا۔ اس کی گود میں شاید غلام علی کا دوسرا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک خوش رنگ بیلون تھا۔ غلام علی دیوانوں کی طرح اس پر جھپٹا۔۔۔ پٹاخے کی سی آواز آئی۔۔۔ بیلون پھٹ گیا اور بچے کے ہاتھ میں دھاگے کے ساتھ ربڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لٹکتا رہ گیا۔ غلام علی نے دو انگلیوں سے اس ٹکڑے کو چھین کر یوں پھینکا جیسے وہ کوئی نہایت ہی مکروہ چیز تھی۔
- کتاب : نمرودکی خدائی
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.