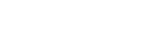کہانی کی کہانی
ایک ایسے بوڑھے شخص کی کہانی جو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں تنہا رہتے ہوئے بور ہو گیا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا تو گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر اور سامان بیچتے دوکاندار سے بات کرنا اسے اچھا لگا۔ اس طرح وہ وہاں روز آنے لگا اور اپنا وقت گزارنے لگا۔ ایک دن انگلینڈ سے واپس آیا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کافی وقت کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اور پھر سے اپنی گلی میں نکلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آگئی ہے، شاید وہ ان کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔
رحمت خاں خاصا طویل تھا۔ دور دور تک پرانے مکانوں کی دو رویہ قطاریں پھیلی ہوئی تھیں، آخر میں جہاں آنے جانے والوں کے لیے راستہ بند کرنے کی خاطر ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی۔ آمنے سامنے پانچ دکانیں اس کوچے میں رہنے والوں کی ضرورتیں پوری کر رہی تھیں۔ ان دکانوں سے کچھ دور، دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک تخت بچھا رہتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ تخت کب بچھایا گیا تھا اور اس کو بچھانے والا کون تھا اور یہ جاننے کے لیے کسی کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ دکانداروں کو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی دقت نہیں تھی اور نہ اس پر کسی کو اعتراض تھا۔ کسی دکاندار کو دن بھر کے لیے کہیں فالتو سامان رکھوانے کی مجبوری ہوتی تھی تو وہ بلاتکلف اپنی یہ چیزیں اس تخت پر ڈھیر کردیتا تھا اور دکان بند کرتے وقت انھیں اٹھوا لیتا تھا۔
یہ تخت عام طور پر سامان رکھوانے ہی کے کام آتا تھا مگر چند ماہ سے اس مصرف کے ساتھ ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھی یہاں دن کا بیشتر حصہ گزارنے لگا تھا، یہ شخص جس کا نام حسین احمد تھا۔ خود اس کوچے میں نہیں رہتا تھا۔ دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ صبح سویرے آ جاتا تھا او ردوپہر کے آدھ پونے گھنٹے کے وقفے کے سوا شام تک یہیں پرا رہتا تھا۔
دکاندار اس سے حوش تھے۔ کیونکہ انھیں اس شخص کے روپ میں ایک قسم کا نوکر مل گیا تھا۔ ایک ایسا نوکر جو کسی سے پیسہ بھی نہیں لیتا تھا اور ہر ایک کا کام بخوشی کر دیتا تھا۔ کسی کو کسی ضرورت سے گھر جانا پڑتا تھا تو وہ اسے دکان میں بٹھاکر چلا جاتا تھا اور دکان کی طرف سے بےفکر ہو جاتا تھا۔
حسین احمد کے لیے ان پانچ دکانوں میں سے چار دکانوں کے اندر بیٹھ کر ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے سودا بیچنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ بشیر اور راشد کی دکانوں میں دالیں، آٹا اور ایسی ہی اشیائے صرف بکتی تھیں اور وہ ان کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ تیسری دکان بوتلوں اور پان سگریٹ کی تھی۔ اس سے ملحقہ دکان میں ڈبل روٹی، انڈے، اچار، جام اور اس قسم کی چیزیں دستیاب تھیں۔ پان سگریٹ کی دکان کا کرایہ دار ابراہیم تھا اور ڈبل روٹی اور انڈوں کی دکان میں خود بیٹھتا تھا۔ ان دکانوں میں بھی بیٹھنے اور وقتی طور پر انھیں چلانے میں حسین احمد کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ البتہ پانچویں دکان جو افضال درزی کی تھی۔ یہاں وہ صرف بیٹھ کر دکان کی چیزوں کی نگرانی ہی کر سکتا تھا۔ درزی کا کام کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔
حسین احمد کا تخت پر بیٹھ کر دکانداروں کی کچھ دیر کے لیے ذمے داریاں نبھانا، ایک حادثے کا نتیجہ تھا۔ اس نےاپنی پوری زندگی میں دکانداری نہیں کی تھی، وہ تو میٹرک کرنے کے بعد ایک دفتر میں بطور کلرک کے بھرتی ہوا تھا اور جوں کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر پہنچا تھا اور جب اس عہدے پر پہنچا تھا تو اس سے صرف ایک سال بعد مقررہ قواعد کے مطابق ریٹائر کر دیا گیا تھا۔
ریٹائر ہونے کے بعد سارا وقت گھر کی چاردیواری کے اندر گزارنا اس کے لیے برا بور کام تھا۔ ایک ماہ تک تو اسے بوریت محسوس نہ ہوئی، دوستوں، عزیزوں نے اپنے گھروں میں چائے کھانے کی دعوتیں دیں۔ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ گھر کا سامان از سر نو ترتیب سے رکھا۔ کتابوں کے لیے الماری خریدی۔ اس میں پرانی اور نئی کتابیں رکھیں۔ اسی طرح تیس دن بیت گئے۔ اگلے مہینے کے لیے اس کے پاس اس نوعیت کا کوئی کام نہیں تھا۔ مشکل یہ تھی کہ بیوی کو فوت ہوئے دس برس گزر چکے تھے۔ بیٹیاں ماں کے انتقال کے بعد باپ کا سارا سرمایہ اور جمع جتھا سمیٹ کر انگلینڈ میں جابسا تھا۔ جہاں اس نے شادی بھی کرلی تھی۔
بیٹی شادی کے بعد امریکہ اپنے شوہر کے ہمراہ جا چکی تھی۔ گھر میں وہ تنہا رہ گیا تھا۔
دفتر میں کام کرتا تھا تو آدھا دن وہیں گزر جاتا تھا۔ کچھ وقت کسی کے ہاں جاکر تاش وغیرہ کھیل کر گزار دیتا تھا۔ شام کے بعد گھر آتا تھا۔ کھانا کھاکر کچھ دیر پڑھتا تھا پھر سوجاتا تھا۔ دوسرے روز پھر یہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔
اس کے مکان کے دو حصے تھے۔ اوپر کی منزل میں اس کی رشتے میں ایک بہن زینب نام کی رہتی تھی۔ جس کے بچوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ یہ بھی بڑی بات تھی کہ وہ رات کا کھانا اس کے لیے نیچے بھجوا دیتی تھی۔ ناشتا اور دوپہر کا کھانا حسین احمد دفتر کی کینٹین میں کھاتا تھا یا دل چاہتا تھا تو ایک قریبی ہوٹل میں چلا جاتا تھا۔
اس کوچے کی دکانوں سے وہ عموماً سودا سلف نہیں خریدتا تھا۔ ہاں کبھی زینب کہتی تھی تو آٹا، دال یا کوئی اور شے خرید لاتا تھا۔ اس روز بہن کی فرمائش پر وہ چاول خریدنےگیا تھا۔
دکاندار بشیر کے ہاں اس وقت چاول تھے نہیں۔ بولا۔
’’جناب پوری آنے ہی والی ہے، بڑی جلدی۔ آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں!‘‘
دکاندار نے تخت کی طرف اشارہ کیا تھا، حسین احمد نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ضرورت کی چیز دوسری دکان سے خریدے۔ اس لیے چپ چاپ تخت پر جا بیٹھا۔
وہاں بیٹھ کر اسے عجیب لطف آیا۔ دائیں بائیں حد نگاہ تک مکان ہی مکان، کچھ دوتین منزلہ اونچے، کچھ ایک منزلہ چھوٹے، دروازوں میں سے لوگ نکلتے ہوئے اندر جاتے ہوئے، کوئی کسی دروازے پر دستک دیتا ہوا، کوئی کسی مکان کے سامنے کسی سے مصروف گفتگو، کوئی بچے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مکانوں کی دائیں قطار کے آگے ایک لڑکا ہاتھوں میں فٹ بال اٹھائے بھاگ رہا تھا اور اس کا تعاقب ایک بچی کر رہی تھی۔ جو یقیناً اس کی بہن ہوگی۔ دونں کے چہرے فطرِ مسرت سے دمل رہے تھے۔ ایک جگہ ایک شخص مختلف چیزوں سے لدا پھندا ایک عورت کے پہلو بہ پہلو قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ عورت نے بھی دائیں ہاتھ میں ایک سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا۔ عورت مرد کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ مستقبل کے خوشگوار خوابوں میں رچی بسی تھی۔ ایک نوجوان کبھی ادھر دیکھتا تھا اور کبھی ادھر اور پھر جلدی سے اوپر اس چک پر نظریں ڈال دیتا تھا جسے لمحہ بہ لمحہ جنبش ہو رہی تھی۔
زندگی کے یہ سارے مناظر اسے پیارے لگے۔ اس نے یہ سب کچھ بارہا دیکھا ہوگا۔ مگر اپنے منصبی فرائض کے ہجوم میں ان کا کبھی خیال نہیں کیا تھا۔ لیکن اس روز یہ ساری سرگرمیاں اسے دلچسپ لگ رہی تھیں اور اس کا جی چاہتا تھا کہ انھیں کچھ دیر کے لیے دیکھتا رہے۔ وہ وقتی طور پر یہ بھول ہی گیا تھا کہ گھر سے چاول لینے کے لیے نکلا ہے اور اس تخت پر ایک دکاندار کے کہنے پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ گاہک دکانوں پر آ جا رہے تھے اور اس کو ایک لمحے کے لیے دیکھ کر سودا لینے میں مصروف ہو جاتے تھے۔
وہ تخت پر بیٹھا رہا۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک معصوم سے قہقہے گونجے۔ کوئی شےاس کے پاؤں کو چھونے لگی۔
اس نے اپنے قریب ہی اسی بہن اور اس کے بھائی کو دیکھا جو چندمنٹ پہلے اس سے کچھ دور بھاگ رہے تھے۔
’’یہ میرا ہے۔‘‘
’’نہیں یہ میرا ہے۔‘‘
فٹ بال اس کے پاؤں کے پاس پڑا تھا اور بیک وقت چار ننھے ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھے ہوئے تھے۔
’’او بدتمیزو!‘‘ یہ گرجدار آواز بشیر کی تھی جو بچوں کو ڈانٹ رہا تھا۔
بچے خاموش ہو گئے تھے مگر انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں کھینچے تھے۔
حسین احمد نے فٹ بال ہاتھوں میں پکڑ لیا۔
’’بیٹھ جاؤ۔‘‘
بچے تخت پر بیٹھ گئے۔ اس نے فٹ بال بچی کی گود میں رکھ دیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر فوراً اٹھی اور بھاگ گئی۔ اس کا بھائی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ منظر دیکھتا رہا۔ یہاں تک کہ دونوں بچے کوچے کے دوسرے سرے پر پہنچ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔
’’لیجیے جناب!‘‘ بشیر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔
اس نے لفافہ تھام لیا اور دکاندار کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔
’’سات روپے۔‘‘
اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور کب چاولوں کے پیسے بشیر کے ہاتھ میں رکھے تھے۔
یہ اس کا تخت پر بیٹھنے کا پہلا تجربہ تھا۔
چاولوں کالفافہ زینب کو دیتے ہوئے اس نے کہہ دیا۔
’’زینب! دیکھو! آئندہ کوئی چیز منگوانی ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرو۔‘‘
’’بچے جو ہیں۔‘‘
’’نہیں۔ میں لایا کروں گا۔‘‘ اس کا فیصلہ تھا۔
پہلے تجربے نےاسے ایسی خوشی دی تھی کہ وہ سودا لینے کے لیے جب بھی کسی دکان پر جاتا تھا، دکاندار سے کچھ کہنےکے بعد تخت پر جا بیٹھتا تھا۔ اس طرح تخت اس کے اور دکانداروں کے درمیان روابط استوار کرنے کاذریعہ بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور یہ روابط بڑھتے چلے گئے۔
گھر میں اس کے لیے سوائے کتابوں کے مطالعے کے کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ اس لیے وہ باقاعدہ وہاں بیٹھنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ دن کا ایک معقول حصہ خوشگوار ماحول میں گزر جاتا ہے اور دکانداروں نے اس اعتبار سے اسے غنیمت سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنی اپنی دکانوں سے نکل کر کوئی نہ کوئی کام کاج کر لیتے تھے اور گاہکوں کی طرف سے انھیں کوئی فکر نہیں ستاتی تھی۔ حسین احمد نے اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان کی عدم موجودگی میں گاہکوں سے نمٹ سکتا تھا۔
کسی دکان پر شور، دوسروں سے پہلے سودا لینےکی جدوجہد، ہلکی پھلکی لڑائیاں، طعنے، مذاق، فقرہ بازی۔۔۔ ان سب چیزوں سے وہ خوش ہوتا تھا۔ دکانداروں سے بے تکلفی بڑھی تو آپ سے مخاطبت تم تک پہنچی۔ پہلے وہ اسے حسین احمد کہتے تھے۔ پھر ’’گنجو‘‘ کہنے لگے۔ مدت ہوئی وہ سر کے بالوں کے معاملے میں فارغ البال ہو چکا تھا اور اس کی یہی خصوصیت اسے ’’گنجو‘‘ کہلوانے کی ذمے داری تھی۔
کوئی دکاندار جب اسے مخاطب کرکے کہتا تھا، ’’آیار گنجو۔ جا رہا ہوں۔ بیٹھ گدی پر۔‘‘ تو وہ برا نہیں مانتا تھا کہ اس انداز تخاطب میں ایک گہرا خلوص تھا اور محبت تھی۔
اس میں اور دکانداروں میں بے تکلیفی کا احساس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ابراہیم تو اسے آواز بھی نہیں دیتا تھا۔ چٹکی بجاکر اسے مخاطب کرتا تھا اور دایاں ہاتھ لہراکر روانہ ہو جاتا تھا۔ حسین احمد کو اس کی یہ ادا بڑی پسند تھی اور وہ اس پر مسکرائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ صمد چٹکی کی بجائے تالی بجاتا تھا اور جب وہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس وقت چٹکی بجا دیتا تھا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بڑی جلدی واپس دکان پر آ جائےگا۔
روز بروز یہ بے تکلفانہ روابط بڑھتے جا رہے تھے۔
حسین احمد جب تک ۱پنی چار دیواری کے اندر رہتا تھا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ زینب اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ ’’بجان تم دکانداروں ے نوکر بن گئے ہو۔ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ گھر میں آرام سے بیٹھا کرو۔‘‘ مگر وہ اس کے جواب میں ہوں ہاں کرکے رہ جاتا تھا اور زینب کچھ مایوس ہو جاتی۔ اصل میں اس کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ حسین احمد کی عدم موجودگی میں زینب کے بچے ماں کی نظر بچاکر نیچے چلے جاتے تھے اور حسین احمد کی چیزوں کو خراب کر دیتے تھے۔ حسین احمد اس کی شکایت کرتا تھا تو زینب ایک لمحہ تال کیے بغیر کہہ دیتی تھی۔ ’’بھجان نہ جائیں آپ وہاں بچوں کو لاکھ روکو، کرماں مارے باز آتے ہیں۔‘‘
زینب اپنے شوہر کو ناشتا دینے ے بعد عام طور پر حسین احمد کے لیے ناشتا لے کر اس کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ کبھی نہیں بھی آ سکتی تھی تو وہ زیادہ انتظار نہیں کرتا تھا۔ اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ وہیں ناشتا کر لیتا تھا۔
اس روز وہابھی چارپائی سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ اسے زینب کے قدموں کی مانوس آہٹ سنائی دی۔
’’یہ آج اتنی جلدی کیوں آ گئی ہے؟‘‘ اس نے کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔
زینب کے ہاتھ میں معمول کے مطابق ناشتے کی ٹرے نہیں تھی بلکہ ایک لفافہ تھا۔
’’بھجان!‘‘
حسین احمد اٹھ کر بیٹھ گیا اور نگاہوں سے استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے۔
’’یہ تار کل آیا تھا۔ تم گھر میں تھے نہیں۔‘‘
حسین احمد نے لفافہ لے لیا، کھولا۔ انگلینڈ سے اس کے بیٹے الطاف نے بھیجا تھا اور پاکستان میں آنے کی اطلاع دی تھی۔
’’الطاف کا ہوگا؟‘‘ زینب نے کہا۔
’’ہاں۔ آ رہا ہے۔‘‘
’’آ رہا ہے۔ سچ؟‘‘
’’تار میں تو یہی لکھا ہے۔‘‘
دوسرا تار الطاف نے کراچی پہنچ کر دیا کہ وہ جمعرات کو شام چھ بجے لاہور ائرپورٹ پر پہنچ جائےگا۔
جمعرات کو پانچ بجے وہ ائرپورٹ میں تھا۔
چھ کی بجائے ساڑھے چھ بجے جہاز نے ائرپورٹ پر لینڈ کیا اور حسین احمد کو آدھ گھنٹہ اور بیٹےکا انتظار کرنا پڑا۔
وہ اپنے بیٹے کے علاوہ چار اور چہرے بھی دیکھ رہا تھا۔
ایک خوبصورت میم۔ دو لڑکے اور ایک لڑکی۔
میم ادب اور احترام سے اپنا سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بچے اپنے دادا کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا باپ سے گرمجوشی کے ساتھ بغل گیر ہونے کے بعد پوچھ رہا تھا۔
’’اباجان! آپ بالکل ٹھیک ہیں نا۔‘‘
’’ہاں پتر۔ ٹھیک ہوں۔ آج تیری ماں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔‘‘ حسین احمد ی آنکھیں بھیگ گئیں۔
’’یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ابا جان۔‘‘
ائرپورٹ کے باہر سفید رنگ کی ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ یہ الطاف کا ایک دوست الطاف اور اس کی فیملی کے لیے لایا تھا۔
کار میں بیٹھ کر الطاف باپ سے وہ حالات پوچھتا رہا جو اس کی غیرحاصری میں اسے پیش آئے تھے۔ مگر حسین احمد یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کار شہر کے اندر جانے کی بجائے کہیں اور جا رہی تھی اور جس راستے پر جا رہی تھی اس سے وہ واقف نہیں تھا۔ شہر میں وہ بہت کم گھوما پھرا تھا اور نئی آبادیوں کے معاملے میں تو بالکل کورا تھا۔
پندرہ بیس منٹ بعد کار ایک شاندار ہوٹل کے وسیع پورچ میں رک گئی۔
’’اباجی۔‘‘ الطاف کار سے اترتے ہوئے بولا، ’’جب تک رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میرا قیام یہیں رہےگا۔‘‘
’’ہوٹل میں؟‘‘
’’ہاں اباجی۔‘‘
’’مگر الطاف اپنا گھر۔‘‘
’’اب اس گھر میں کون جاتا ہے انکل! آپ کا بیٹا ڈاکٹری کی بڑی ڈگریاں لے کر آیا ہے۔ وہاں رہنا اس کی شان کے خلاف ہے۔‘‘ الطاف کی بجائے اس کے دوست نے وضاحت کی۔
’’میں گھر آؤں گا۔ مگر ابھی نہیں۔ ابھی تو سخت بزی ہوں۔ آنٹی زینب سے کہہ دیں میں آؤں گا۔‘‘
کمرے میں داخل ہوتے ہی الطاف نے ٹیلی فون سنبھال لیا اور آدھ گھنٹے کے بعد لوگ آنے لگے۔
قہقہے، مبارکبادیں، بے تکلفانہ گفتگو، معانقے، مصافحے، حسین احمد ایک طرف بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اسے اس طرح فراموش کر دیا گیا تھا جیسے وہ ایک زندہ انسان نہیں، کمرے کے فرنیچر کا کوئی حصہ ہے۔ جیسے صوفہ سیٹ، میز، دیوار پر لگی ہوئی کوئی تصویر، ٹیبل لیمپ۔ اسے یہ ماحول اجنبی سا، غیرمانوس سا لگ رہا تھا۔ بیرا بار بار چائے لے کر آ رہا تھا۔ نئی ٹرے آئی تو الطاف باپ سے پوچھا۔
’’چائے چلےگی ابا جی۔‘‘
’’نہیں۔ بہت پی چکا۔‘‘
اباجی، کے لفظ پر الطاف کا نیا آنے والا دوست حسین احمد پر ایک نظر ڈال کر سلام کے انداز میں اپنا سر ذرا خم کر دیتا اور پھر خالی صوفے پر بیٹھ جاتا۔ شام تک یہی گہما گہمی رہی۔
بیٹے نے محسوس کر لیا کہ باپ بور ہو رہا ہے۔ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔
’’اباجی۔ آپ کچھ۔‘‘
باپ نے سمجھ لیا کہ بیٹا کسی خدشے کااظہار کرنا چاہتا ہے۔
’’ہاں الطاف تم اپنےدوستوں سےملو۔ میں کیا کروں گا یہاں بیٹھ کر۔‘‘
’’کھانا کھاکر جائیے گا۔‘‘
حسین احمد اٹھ بیٹھا۔
’’نہیں۔ میں رات کا کھانا دیر سے کھاتا ہوں، بس اب مجھے جانے دو۔‘‘
وہ دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ الطاف کےسارے دوست اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
’’میرا احترام کر رہے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے سینے میں خوشی اور فخر کی ایک لہر سی دور گئی۔ لیکن جب وہ الطاف کے دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر جا رہا تھا تو یہ لہر نہ جانے کیوں ڈوب گئی تھی اور اس کی بجائے ایک مبہم سی افسردگی اس کے ذہن پر چھا گئی تھی۔
زینب نے اسے تنہا گھر کی طرف آتے دیکھ تو حیران ہوکر پوچھا۔
’’بھجان! الطانف نہیں آیا؟‘‘
حسین احمد نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
’’آیا ہے؟‘‘ زینب کا دوسرا سوال تھا۔
’’ادھر آئےگا۔ بہت سے دوست آ گئے تھے۔ انھیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آئےگا۔ میں نے کہا نا۔‘‘
زینب خاموش رہی۔ حیرت اور استفسار کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی اور جب اسے اس کا بھائی جان مزید کچھ کہنے سننے کے موڈ میں نہیں تو اس نے اپنا سر اس انداز سے جھٹک دیا کہ جیسے کہہ رہی ہو، ’’تمہاری مرضی۔‘‘
زینب کے جانے کے بعد اس نے جلدی جلدی لباس تبدلی کیا اور خود کو چارپائی پر گرا دیا۔ اچانک اسے اپنی بیوی یاد آگئی اور اس کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں، دیر تک وہ بیوی کی یادوں میں گم صم لیٹا رہا اور پھر سو گیا۔
صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہوکر اپنی روشنی کھڑکی کے راستے اس کے کمرے میں پھیلا چکا تھا۔ اس کی طبیعت کسل مند تھی۔ اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا تو وہ گرم تھا۔
ایک ہفتہ وہ بخار میں مبتلا رہا۔ بخار کی شدت میں گھر سے باہر ہی نہ نکل سکا۔ آٹھویں روز اس کی طبیعت بحال ہوئی تو الطاف آ گیا۔
دوگھنٹے اس نے اپنے پرانے مکان میں گزارے اور جب جانے لگا تو باپ سے کہنے لگا۔
’’اباجان! میں نے کوٹھی خرید لی ہے۔ چلیے میرے ساتھ۔‘‘
’’میں یہاں ٹھیک ہوں بیٹا! آخر مجھے یہاں کیا تکلیف ہے۔‘‘
’’تکلیف کی بات نہیں ابا جان! میں واپس آ گیا ہوں تو آپ تنہا کیوں رہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آپ کی عمر کا یہ حصہ بڑے آرام اور سکون سے گزرنا چاہیے۔‘‘ اور الطاف باپ کو کار میں بٹھاکر اپنے ہاں لے گیا۔
ایسی خوب صورت کوٹھی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ نہایت اعلیٰ قسم کا سازوسامان خدمت کے لیے ایک چھوڑ کئی نوکر، اسے تنکا توڑنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دنپر دن گزرتے گئے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے دل میں ایک خواہش نے سر اٹھایا، اسے اپنا پرانا ماحول، اپنے ساتھی یاد آنے لگے۔ راتوں کو سونے سے پیشتر اس کو تنہائی کے لمحے میسر آتے تو وہ واپس اپنی دنیا میں چلا جاتا۔ جہاں اس نے خوشی بھرے دنگزارے تھے۔جہاں بشیر تھا اور ارشد تھا، ابراہیم، صمد اور افضال تھے۔ جہاں دو رویہ پرانے مکان دور تک کھڑے تھے۔ یکایک شرارت سے دمکتے ہوئے چہرے اس کے چاروں طرف روشنی سی بکھیرنے لگتے اور وہ پلنگ پر کروٹیں بدلنے لگتا۔
دن بیت رہے تھے اور اپنی دنیا میں واپس جانے کی خواہش اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔
اپنی اس آرزو کا اظہار وہ کسی سے کر بھی نہیں سکتا تھا۔
’’الطاف بیٹا۔‘‘ اس دن اس کے بیٹے کو ذرا فرصت تھی۔
’’جی ابا جان! کیا بات ہے؟‘‘
’’وہ۔ بیٹا! میں ذرا اُدھر۔۔۔ جانا چاہتا ہوں۔‘‘
’’ادھر کہاں اباجان!‘‘
’’اُ۔د۔دھر۔ اپنے محلے میں۔‘‘
’’کیا کریں گے وہاں جاکر؟‘‘ بیٹے نے پوچھا۔
’’کرناکیا ہے اپنے ساتھی یاد آرہے ہیں۔‘‘
الطاف دو تین لمحے سوچ کر بولا۔
’’ابا جان؟ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں۔ جی چاہتا ہے تو چلے جائیے۔‘‘ اور الطاف نے ڈوائیور سے کہہ دیا، ’’ابا جان کو لے جاؤ۔‘‘
کار شاداب سڑکوں سےگزر کر گردوغبار سےاٹے ہوئے راستے پر آ گئی اور پھر وہی مکان، وہی لوگ، وہی نیم تاریک فضا۔
وہ کار سے اتر پڑا اور جب ایک طرف چلنے لگا تو اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔
وہ لمبی گلی ویسی کی ویسی تھی۔ وہی اس کی رونق تھی۔ اسی طرح لوگ گھروں سے نکل رہے تھے۔ گھروں کے اندر جا رہے تھے۔
دروازوں پر دستک دی جارہی تھی۔ اوپر چقیں ذرا ہٹا ہٹاکر بوڑھے، جوان، نوعمر چہرے جھانک رہے تھے۔
ایک بچی فٹ بال لیے بھاگ رہی تھی اور اس کا بھائی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔
سامنے۔ دور۔ ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ جو خالی نظر آ رہا تھا۔
گاہک دکانوں کے سامنے کھڑے تھے۔
اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ اس کے کانوں میں بیک وقت کئی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس روشنی میں ایک عجیب راحت تھی، ان آوازوں میں ایک ناقابل بیان مٹھاس تھی۔
ایک انجانی خوشی اسے آگے ہی آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہی تھی اور وہ چلا جا رہا تھا۔ تخت پر نگاہیں جمائے ہوئے۔ ان نظروں سے بےخبر جو اس کے ساتھ ساتھ جارہی تھیں۔ پہلی دکان افضال درزی کی تھی۔ وہ سر جھکائے مشین چلا رہا تھا۔
وہ رک گیا۔ افضال نے اسے دیکھا۔ مشین کی ہتھی چھوڑ کر باہر آ گیا۔
’’آئیے حسین احمد صاحب۔‘‘
اسے محسوس ہوا کہ ایک اجنبی آواز اس کے ذہن سے آکر ٹکرائی ہے۔
اسے دیکھ کر ابراہیم، صمد، بشیر اور راشد بھی اپنی اپنی دکانوں سے نکل کر آ گئے۔
کسی چہرے پر کوئی شرارت کا رنگ نہیں تھا۔ کوئی چہرہ اپنائیت کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب ادب اور احترام سے بول رہے تھے۔
’’آپ کی طبیعت کیسی ہے حسین احمد جی!‘‘
’’کیا حال ہے آپ کا؟‘‘
’’کوئی خدمت ہمارے لائق۔‘‘
یہ کون لوگ ہیں۔ جو اس طرح مجھ سے میرا حال پوچھ رہے ہیں۔ کیا یہ وہی ساتھی ہیں میرے، جو گھڑی گھڑی میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مجھے ’’گنجو‘‘ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہی تو ہیں مگر انھیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟‘‘
اور وہ اپنے پرانے تخت پر جا بیٹھا۔ سب اس کے اردگرد کھڑے تھے۔
’’رستم! گرم چائے لاؤ۔‘‘
گرم چائے میرے لیے۔ وہ کیوں۔ پہلے تو ان میں سے کسی نے ایسا تکلف نہیں کیا تھا۔ اس کے اردگرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔
وہ پوچھنا چاہتا تھا یارو! تم نے مجھے پہچانا بھی ہے۔ مگر ہر بار یہ آواز اس کے باطن سے اٹھ کر وہیں جذب ہو جاتی تھی۔
’’یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اپنے پرانے محلے میں آئے ہیں۔‘‘
نہ جانے یہ الفاظ کس نے کہے تھے۔
وہ جھنجھلا اٹھا۔
’’یارو!‘‘ اس نے اپنا دایاں ہاتھ لہرایا۔
’’مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں۔‘‘
چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک آواز اٹھی۔
’’ہاں۔ آپ شہرکے ایک بڑے ڈاکٹر الطاف احمد کے ابا جان ہیں۔‘‘
یہ آواز ایک بھاری پتھر بن کر اس کے اوپر گری۔
مچھر سیاہ بادل اس کے اوپر چھا گئے اور ان سیاہ دلوں کے اندھیارے میں وہ بھاری بھاری قدم اٹھاکر لمبی گلی سے باہر نکلنے لگا۔
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.